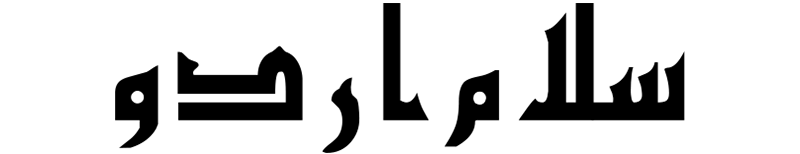پریم چند مرتے کیوں نہیں؟ ۔ ڈاکٹر نور ظہیر
نارائنی کی جھنجھلاہٹ جائز تھی۔ بیس سال کی پترکاریتا اور آٹھ الگ الگ اخباروں اور رسالوں کی نوکری میں لگ بھگ ہر چیز بدل چکی تھی۔ تنخواہ، عہدہ، کمرہ، بلڈنگ، یہاں تک کہ بھاشا بھی۔ بس ایک تو وہ نہیں بدلی تھی اور ایک یہ اسائنمنٹ۔ اس کی نہ بدلنے کی وجہ کیا تھی یہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آخر اور بھی تو لوگ تھے جو پریم چند پر لکھ سکتے تھے۔ ایڈیٹوریل بورڈ میں ہی، ایک تو ان پر پی ایچ ڈی کیے بیٹھے تھے۔ لیکن نہیں! جہاں پریم چند جینتی آئی، پریم چند پر کوئی سیمینار ہوا، ان کے نام سے کسی انعام کا اعلان ہوا کہ بس! بلاؤ نارائنی کو۔ مانا اس نے پریم چند پر اپنا پہلا لیکھ، بڑا من لگاکر اور کافی تحقیق کرنے کے بعد لکھا تھا۔ لیکن بھئی، تب وہ بائیس سال کی تھی۔ یہ بات بھی مان لی کہ اس کے پِتا اس سنگٹھن میں شروع سے تھے جو بعد میں چل کر پورے دیش میں پھیلا اور جس کی پہلی کانفرنس کا افتتاحی اور صدارتی تقریر پریم چند نے کی تھی۔ لیکن اس کے یہ مطلب تو نہیں کہ آج بیس سال بعد، 44 کی عمر میں بھی جب کوئی ایڈیٹر چاہے، پریم چند کو اس کے متھے چیپ دے۔اتنی بار کوئی نئی بات لانا، ایک ہی شخصیت کے بارے میں کیسے ممکن ہے؟ تنگ آکر اس نے ایک بار، ہفتہ وار میٹنگ میں طنز کرکے کہا بھی تھا کہ اب ادیبوں کو چاہیے کہ پریم چند کو چین سے رہنے دیں۔ کیوں ان بیچارے کی ایسی گت بنائی جارہی ہے کہ وہ شعر یاد آتا ہے:
اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے
مرکے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے
لیکن یہ ادیب کہاں ماننے والے۔ دے برسی پر برسی، سیمینار پر سیمینار، کانفرنس، شتابدی، 125 واں جنم دن۔ اور یہ پریم چند بھی ڈھیٹ کے ڈھیٹ ، مرتے ہی نہیں۔
پیں پیں ! نارائنی کے ٹھیک پیچھے ہارن بجا۔ وہ اچھل کر ایک طرف ہوگئی اور گھورتے ہوئے گاڑی والے کو پلٹ کر گھورنے کی کوشش کرتی ہوئی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ باراکھمبا روڈ کا یہ حصہ، نیا نیا میٹرو ریل کی پکڑ سے آزاد ہوا تھا۔ صاف ستھری، نئی تارکول بچھی، چکنی سڑک نکل آئی تھی جیسے کسی ماڈل کی ویکسنگ کے بعد دمکتی گداز بانہیں۔ نارائنی فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی ہیلی روڈ کے موڑ پر رُک کر کھڑی ہوگئی۔ کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ساہتیہ اکادمی کی لائبریری کھلی مل جائے گی۔ وہیں چل کر پریم چند پر کچھ نئی کتابیں دیکھی جائیں یا گھر جاکر کچھ الگ ہی سوچا جائے؟
وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے پاس بدبو کا ایک بھبھکا آیا۔ نارائنی نے ناک پر ہاتھ رکھ کر، دو قدم آگے بڑھ کر پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ جہاں وہ کھڑی تھی اس کے ٹھیک پیچھے ایک سیویج مین ہول کھلا ہوا تھا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے ہی مین ہول سے دو ہاتھ باہر آئے۔ کالی کٹی پھٹی انگلیوں نے فٹ پاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور پورے جسم کو گڈھے میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ باہر آتے ہی ایک جھٹکے کے ساتھ شریر گھوما اور کگار پر بیٹھ گیا۔ نارائنی کی طرف آنے والی بدبو بڑھ گئی۔ پھر شاید اندر سے کسی نے کچھ کہا۔ اس نے ٹانگیں باہر نکالیں اور دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر سر اندر کو بڑھایا۔ بات سن کر اس کے چہرے پر ذرا گھبراہٹ سی نظر آنے لگی۔ بولا — ”پانی کہاں سے لاؤں؟“
اب ایک اور ہاتھ، گڈھے کی کگار پر آیا اور اندر سے آواز آئی — ”ارے کسی بھی بنگلے سے مانگ لے۔“
”مانگنے سے پانی دے دیں گے؟“ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑھ گئی۔
”کاہے نہیں دیں گے۔ ارے انہی کا تو سب میلا کچیلا صاف کررہے ہیں۔ پانی ہی تو مانگ رہے ہیں، اِتّا بھی نہیں کریں گے؟“
”پانی تو میں لے آؤں گا، پر بوتل کہاں ہے؟“
نارائنی کو اندر سے آنے والا جواب سنائی نہیں دیا مگر اسے ضرور جواب مل گیا ہوگا کیونکہ وہ اٹھا اور پاس ہی مولسری کے ایک گھنے پیڑ کی جڑوں پر سوکھے پتوں کے ڈھیر سے اس نے ایک پلاسٹک کی دو لیٹر کی بوتل نکالی۔ بوتل ہاتھ میں لے کر وہ ہیلی روڈ پر مڑگیا۔
لال رنگ کی پرانی سی، دو جگہ سے گھس کر چھدری ہوگئی بنیان اور اتنی ہی پرانی، گھٹنوں سے ذرا نیچے تک مڑی جینس پہنے، سر پر تنگ سی کیپ جو کبھی سفید رہی ہوگی اور اب میلی بھوری سی تھی، جسے وہ سورو گانگولی سٹائل میں الٹی پہنے ہوئے تھا۔ رنگ بے حد تپا ہوا اور پورے تن پر کئی جگہ، کالے، لبلبے کیچ کے چھینٹیں، کچھ پرانے جو سوکھ کر پپڑیا گئے تھے، کچھ نئے، جو ابھی ایک چمکدار، بہتی لجلجی لکیریں بنارہے تھے۔ جو ایک جھلک نارائنی نے اس کے چہرے کی دیکھی تھی، اس سے بس اتنا ہی اندازہ ہوسکا تھا کہ وہ کوئی سولہ سترہ سال کا تھا۔ داڑھی مونچھ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ہاں، ہونٹوں کے اوپر سیاہی ضرور تھی۔ موٹے موٹے ہونٹ اور سادھارن سی بڑی آنکھیں۔ قد زیادہ اونچا نہیں تھا، شریر بھی دُبلا پتلا تھا، جس پر محنت کرکے کھانے والوں کے جسم والی مچھلیاں ترنگیں مار رہی تھیں۔
کیا معلوم کیوں، نارائنی اس کے پیچھے ہولی۔ وہ کونے کی دو بڑی بلڈنگوں اور ان کے آس پاس کے ٹریفک کو پار کرکے ہیلی روڈ کے بنگلوں کے آگے بنے چھایادار فٹ پاتھ پر نکل آیا تھا۔ نارائنی ذرا سی دوری بنائے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ پانی کہاں سے لاتا ہے؟ شاید۔۔۔
چلچلاتی گرمی کے دنوں میں اسے جو ہری گھنی چھایا ملی یا شاید بدبودار سرنگ سے کھلی ہوا میں آجانے کی وجہ سے ہوا ہو، وہ گانے لگا۔ بھونڈا سا کوئی فلمی گیت جس کی تال میں بوتل جھلاتا اور دوسرا ہاتھ نچاتا، پیر میں پہنی ربڑ کی سلیپریں پھٹکارتا وہ پہلے بنگلے کے پھاٹک کی طرف بڑھا۔
بنگلہ پرانا تھا، انگریزوں کے وقت کا۔ زیادہ تر کھڑکیاں بند تو تھیں ہی، ایک آدھ کے پٹ ندارد تھے اور اوپر لکڑی کے پھٹے ٹھونک دیے گئے تھے۔ کسی زمانے میں شاندار رہے بنگلے کی حالت خستہ ہوچلی تھی۔ لان تھا تو لمبا چوڑا اور بڑے بڑے پیڑوں سے گھرا، مگر اس پر کئی جگہ سے گھاس سوکھ کر گنجے چکتے نکل آئے تھے اور پورے لان پر سوکھے پتّے بھی اتنے بکھرے پڑے تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کئی کئی دن اسے بہارا نہیں جاتا۔ لیکن بنگلے کا پھاٹک اب بھی ویسا ہی اونچا اور مضبوط تھا جیسا اس کے امیری کے دنوں میں رہا ہوگا اور اس گیٹ کے پاس بیٹھا ہوا چوکیدار بھی اصلی اور بڑا چوکس تھا۔ اس نے پہلے گانے کی آواز سنی، گردن ٹیڑھی کرکے لڑکے کو نظر بھر دیکھا، پھر یہ بھانپ کر کہ یہ بنگلہ ہی اس لڑکے کا مقصد ہے وہ لپک کر اپنے لکڑی کے تکونے موکھے سے نکلا اور پھاٹک کا جو ایک پاٹ کھلا تھا اسے کھینچ کر بند کرنے لگا۔ پرانے ہونے کی وجہ سے پھاٹک کے زنگ کھائے قبضوں نے دو ایک ہچکولے کھاکر بے وقت بند کیے جانے پر اپنی ناراضگی جتائی۔ اتنی دیر میں لڑکا پاس پہنچ گیا۔ بوتل اوپر کرکے اس نے پوچھا — ”صاب، باہر کے نل سے پانی لے لوں؟“
چوکیدار نے پھاٹک بند کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا — ”آگے بڑھو! سرکاری بنگلہ ہے۔“
لڑکا ایک پل کو ہچکچایا پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ اس کا گانا بند ہوگیا تھا۔
بنگلے کی حد پار کرکے دوسری چہاردیواری شروع ہوگئی۔ یہ تین یا چار پرانے بنگلوں کو توڑکر بنائی گئی ایک ملٹی اسٹوریز، عالیشان بلڈنگ تھی، مکرانا سنگ مرمر سے ڈھکی، خود کو اکیسویں صدی کا تاج محل سمجھتی ہوئی۔ اس بلڈنگ میں رہنے والے وہ تھے جنھوں نے پچھلے بیس پچیس سالوں میں خوب پیسہ بنایا تھا اور یہاں دلّی کے بیچوں بیچ ایک عالیشان فلیٹ لے کر رہ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نوابوں رجواڑوں کے محلوں میں دو دہائی پہلے ہوٹل کھولتے تھے اور آج وہیں پر ماڈلنگ، ماس کمیونی کیشن، ایکٹنگ وغیرہ کے انسٹی ٹیوٹ چلا رہے تھے۔ ہر نئے بزنس میں ان کی انگلیاں غوطہ لگاتیں اور مالامال ہوکر سطح پر لوٹتیں۔ ان بلڈنگوں کی دیکھ ریکھ کا کام سکیورٹی ایجنسیاں کرتی تھیں۔ ان کے مین گیٹ پر چوکیدار نہیں ’واچ مین‘ رہتے تھے — رجسٹر، قلم اور انٹرکام لیے، ہر وقت تعینات۔ انہی میں سے ایک، جو شاید نیا نیا بہار یا پوربی اترپردیش سے آیا تھا، اس مزدور لڑکے کو ذرا ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکا اس کی نظر سے ذرا بڑھاوا پاکر اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں خالی بوتل دیکھ کر بولا — ”کیا پانی چاہیے؟“ لڑکے نے ہاں میں سر ہلایا۔ واچ مین اسے رکنے کا اشارہ کرکے پھاٹک کے بیچ میں پڑا لوہے کا ڈنڈا اوپر کرنے لگا۔ باہر سے ایک سرمئی گاڑی پھسلتی ہوئی، ڈرائیووے کی پٹّی پر پڑی بجری پر سرسراتی ہوئی گزری۔ ڈرائیور نے آواز لگائی — ”واچ مین“۔ پوربیا چوکیدار جو لوہے کا ڈنڈا نیچے کرکے مزدور سے دو باتیں کرنے کے لیے تیار ہورہا تھا، اپنی ٹوپی ٹھیک کرتا ہوا لپکا۔
گاڑی کے پیچھے کا شیشہ نیچے ہوا۔ اندر ایک بہت بنی سنوری عورت، ہلکے رنگ کی شیفون کی ساڑی میں لپٹی بیٹھی تھی۔ ان کے برابر میں ہی ایک پندرہ سولہ سال کی لڑکی، تنگ لو کٹ ٹاپ، بالوں میں فیشن ایبل سنہرے اسٹریکس، ایک بھنوں چھدی جس میں سونے کا چھلّا تھا، کانوں میں کندھے تک جھولتے بوندے۔ لڑکا اس کی ایک جھلک دیکھ کر پھر سے خود بخود گانے لگا۔ لڑکی نے اسے گھورکر دیکھا پھر ٹھنکتی ہوئی ماں سے بولی — ”ممّا، ہاؤ ڈیئر ہی!“
عورت غصے سے چوکیدار کے اوپر پھنکاری — ”اس طرح کے آوارہ لوگوں کو بلڈنگ کے اندر کیوں آنے دیتے ہو؟ تمہیں کس لیے رکھا ہے؟ یہاں کھڑے ہوکر ہر آلتو فالتو آدمی سے گپ مارنے کے لیے؟“
ڈرائیور کے پاس والی سیٹ پر ایک پکّی عمر کے، چکنے سے صاحب بیٹھے تھے۔ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولے — ”آپ گھر جائیے میم، بے بی بھی ساتھ ہیں، میں دیکھتا ہوں۔“ شاید یہ میڈم کے سیکریٹری تھے۔ ٹائی کی ناٹ ٹھیک کرتے ہوئے واچ مین کی طرف آئے۔ لڑکا تب تک کھسکنا شروع ہوچکا تھا۔ وہ راستے میں پڑی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا ہوا، لڑکی کی آواز کی نقل کررہا تھا — ”ہاؤ ڈیرڈی۔۔۔ ہاؤ ڈیرڈی“
لڑکے کی چال سے اُتساہ اور بانکپن ختم ہوچکا تھا۔ بند، بدبودار سرنگ سے باہر، روشنی اور تازی ہوا میں آجانے کا نیاپن بھی جاتا رہا تھا۔ اگلے دو بنگلوں پر بورڈ لگے تھے۔ ایک پر بڑا بڑا لال حروف میں لکھا تھا — ”ڈسپیوٹیڈ پراپرٹی“ اور دوسرے پر دلّی کے بہت بڑے بلڈر کا نام، جو اسی جگہ ایک ملٹی اسٹوریز بنانے والے تھے۔ دونوں ہی بنگلے ویران اور انتظار بھری اداسی سی اوڑھے تھے جیسے جنازہ دفن کردیے جانے کے بعد، بانس کی بنی ارتھی کی حالت ہوتی ہے۔
ہیلی روڈ کا لگ بھگ سرا آگیا تھا۔ وہ اس دیوار کے پاس سے گزرا جس پر آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک بہت پرانی، مغلوں کے وقت کی باؤلی ہے۔ کسی زمانے میں یہ باؤلی اپنے ٹھنڈے میٹھے پانی کے لیے مشہور تھی۔ لیکن آج اسے اے ایس آئی نے ’ورثہ‘ اعلان کرکے، ’پروٹکٹیڈ مونومینٹس‘ میں شمار کرلیا تھا۔ اب یہاں سے پانی لینے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔
نارائنی کے پاؤں تھک رہے تھے۔ ویسے اکثر مزدور طبقے کے کچھ پانے کی جدوجہد میں، ان کے ساتھ چل رہے مڈل کلاس کے پاؤں ایسے ہی پست ہوجاتے ہیں اور وہ منزل آنے سے پہلے ہی جدوجہد کی راہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نارائنی بھی کچھ ایسا ہی کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اس نے دیکھا لڑکا ہیلی روڈ کے کونے کے بنگلے کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ اس کے پورے جسم میں جیسے امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سڑک پار کرکے سکوٹر لے لینے کا ارادہ کررہی نارائنی اُتساہ سے پھر اس کے پاس چلی آئی۔
پرانے قسم کا باقاعدہ بنگلہ تھا، یعنی ایک منزل کا اور چاروں طرف سے کھلی جگہ سے گھرا۔ بنگلے کی حالت اور پورٹکوں میں کھڑی تین الگ الگ قسم کی گاڑیاں، چیخ چیخ کر کہہ تھیں کہ یہ ان گنے چنے ابھیجات لوگوں کا گھر ہے جنھوں نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اتنا بدلا ہے کہ ان کا پیڑھیوں سے چلا آرہا عیش و آرام ابھی بھی برقرار ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر اس مزدور کی آشا کیوں جاگی تھی؟ نارائنی نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر کے سہارے اپنی نظر بھی وہاں لے گئی۔
ایک ذرا ڈھلتی عمر کے صاحب، خود بنگلے کے سامنے کے باغیچے میں پانی دے رہے تھے۔ ذرا موٹے سے، کھچڑی مونچھ، اوسط سے ذرا نکلا ہوا قد، گورا رنگ، صاف، چکنے، مینی کیور کیے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پائپ کی نلی پر انگلی رکھ کر، اس کی تیز دھار کا فوّارہ سا بناکر اپنے چاروں طرف، گہرے ہرے لان میں چھڑک رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا، ہاتھ میں رائٹنگ پیڈ اور قلم تھامے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ان دونوں سے چار پانچ قدم دور ان کی طرف منھ کیے، ایک آنکھ پر کیمرہ چپکائے، ایک اور آدمی تھا۔ شاید صاحب کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے۔ دیوار پر چڑھی بوگین وِلا کی آڑ میں نارائنی ان کے کافی پاس آگئی اور کان لگاکر سننے لگی، وہ انٹرویو بھی دے رہے تھے اور بیچ بیچ میں پاس کھڑے مالی اور بیرے کو ہدایتیں بھی دیتے جارہے تھے۔ شاید یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کیمرہ کے آگے بھی کتنے سہج ہیں۔
وہ آب و ہوا پر بات کررہے تھے۔ ابھیجات ہونے کے ساتھ ساتھ فیشن کانشس بھی تھے۔ نارائنی کی نظر پھاٹک پر لگے بورڈ پر پڑی۔ ویسا، جس پر عام طور سے ’کتوں سے ساؤدھان‘ لکھا ہوتا ہے۔ اس بورڈ پر چار بھاشاؤں میں لکھا تھا — ”کرپیا پالی تھین کی کوئی چیز اندر نہ لائیں۔“ وہ کہہ رہے تھے — ”پالی تھین پر ٹوٹل بین ہونا چاہیے، کسی چیز میں اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، ایک تو یہ سڑتا نہیں، اوپر سے اس میں سے ہوا پانی نہیں گزرتا۔ ایک دن آئے گا جب یہ دھرتی کو پوری طرح سے ڈھک لے گا اور سارے جاندار دم گھٹ کر مر جائیں گے۔ نہیں، ری سائیکلنگ اس کا علاج نہیں ہے کیونکہ جو بایوڈگریبل ہی نہیں اس کا روپ بدل جانے سے اس کی نقصان پہچانے کی طاقت میں تو کمی نہیں آئے گی نا! مالی! کل تک یہ سارا کوڑا باہر ہونا چاہیے۔ پالی تھین سب الگ کرو، پتّے مینیور پِٹ میں ڈالو۔ نہیں، یہ پالی تھین کے لفافے میرے گھر کے نہیں ہیں۔ باہر سے اڑکر آجائیں تو کیا کیا جائے اور پھر یہ نوکر بھی تو باز نہیں آتے۔ یہ پوری کی پوری کلاس ہی ۔۔ لاکھ سمجھایا پر ایجوکیشن۔۔اصل میں ہر چیز کی تہہ میں ایجوکیشن ہے ۔۔ وہ نہیں ہو تو سماج میں کوئی سدھار نہیں ہوسکتا۔“
ان کی نظر، پائپ کی پھوہار کے ساتھ گھومتی ہوئی اس مزدور لڑکے پر آکر رُک گئی جو سکوچایا ہوا، اتنا سارا پانی گھاس میں گرتا دیکھ رہا تھا اور اپنے لیے چند بوندیں مانگنے کا موقع تلاش کررہا تھا۔ ”اب اس مزدور کو ہی دیکھیے ۔۔ یہاں آ ۔۔ دیکھیے اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی بوتل ہے۔ میں نے کیا کہا تھا۔ اس لیبر کلاس نے تو جیسے پالی تھین کی دھوم مچا دی ہے۔ پلنگ، کرسیاں، سٹول تک ان کے گھروں میں پلاسٹک کے ہوتے ہیں۔ کتنا سمجھایا، یار سستی کے پیچھے مت بھاگو۔ کچھ اس دھرتی کی بھی فکر کرو۔ اس کی بوتل کا شاٹ لو۔“ کیمرامین نے گردن گھماکر لڑکے کے اوپر فوکس کیا جو ذرا سکپکاکر پیچھے ہوگیا۔ پیچھے ہوتے ہی اس کا پیر، تازی کھدی ہوئی، پانی دی گئی، کیچڑ سے بھری کیاری میں جاپڑا۔ پاؤں پھسلا اور وہ اگلے ہی پل کیاری میں چِت پیر پھیلائے ہوئے دِکھا۔ پائپ چھوڑ کر صاحب دوڑے اور کیاری کے کنارے کھڑے ہوکر، ہاتھ پیر پھینک پھینک کر چلاّنے لگے۔ دونوں نوکر اور ٹی وی ٹیم بھی بڑی سی کیاری کو گھیر کر کھڑے ہوگئے۔ لڑکا بار بار اٹھنے کی کوشش کررہا تھا اور بار بار پھسل کر پہلے سے زیادہ پھیل کر گر جاتا تھا۔ کیمرہ مین اور انٹرویو کرنے والا نوجوان ہنس ہنس کر دوہرے ہوئے جارہے تھے۔ اندر برآمدے میں بندھے ہوئے ایک السے شیئن اور ایک لبراڈار کتے بھونک کر، اچھل اچھل کر، خود کو اپنی ہی چین سے پھانسی لگائے لے رہے تھے۔ صاحب لال پیلے ہونے کی حد پار کرکے اب جامنی ہوچکے تھے۔ ان کا چلانا بھی بند ہوچکا تھا، صرف گلے اور ناک سے ’ہو ۔۔اُو ۔۔ش‘ کے ہنکارے باہر آرہے تھے جیسے وہ آدمی نہیں، لال کپڑے پر حملہ کرتا ہوا سانڈ ہو۔ آخر مالی اور ایک ڈرائیور نے آکر اسے یوں سنبھال کر باہر نکالا جیسے رات کے بچے گھی کی کٹوری میں گر گئے تل چٹّے کو نکالا جاتا ہے۔
پہلے ان لوگوں نے ہاتھ دھوئے پھر پائپ کی دھار اس لڑکے کی طرف ڈالی۔ ابھی، منہ اور سر سے تھوڑا تھوڑا کیچڑ ہی دُھلا ہوگا کہ سردارجی کے منہ سے پستول کی گولی کی طرح بس ایک ہی شبد نکلا — ”آؤٹ!“ لڑکا سمجھ گیا۔ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ ذرا سی گردن ٹیڑھی کرکے وہ کیچڑ سے سنی، پھسلتی ہوئی چپلیں گھسیٹتا، جینس پر ہاتھ مل کر، تیز دھوپ میں سوکھتی کیچڑ کو رگڑکر صاف کرنے کی کوشش کرتا، پھاٹک کی طرف چلا۔ شرم اور ذلت میں اس کی اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہیں کیچڑبھری کیاری سے اپنی خالی بوتل اٹھالے۔
وہ گیٹ سے باہر نکل کر نارائنی کے پاس سے ہوتا ہوا، اسی راستے پر واپس چل دیا جدھر سے آیا تھا۔ نارائنی کی نظریں کچھ دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں، پھر اس کے اور نارائنی کے بیچ ایک خالی آٹورِکشا آگیا۔ نارائنی نے جلدی سے اسے ہاتھ دِکھاکر روکا اور اپنے گھر کے علاقے کا نام بتاکر بیٹھ گئی۔ گھر کی طرف بڑھتی ہوئی وہ سوچ رہی تھی کہ ٹھاکر کے کنویں میں آج بھی ٹھنڈا، میٹھا شفاف پانی ہے۔ آج بھی جوکھو پیاسا ہے۔ آج بھی گنگا ایک لوٹے پانی کے لیے بھٹک رہی ہے۔ اور پریم چند؟ ۔۔پریم چند زندہ ہیں۔