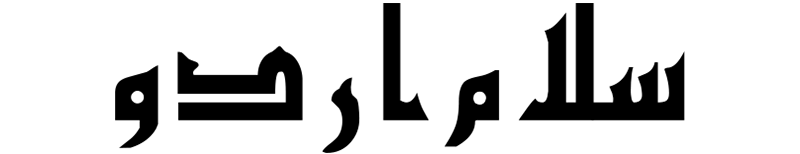سفر نامہ بھارت
امرتسر پہنچے تو امرتسر کے کینال ریسٹ ہاﺅس میں ہمارا قیام تھا۔ شرکاءکی تعداد زیادہ تھی اس لےے ایک کمرے میں چھ چھ سات سات لوگ گُھس گئے۔ پرساد، منجو، کے وانی، وغیرہ ہم ایک کمرے میں تھے۔ میں خوش قسمت تھا کہ مجھے اچھی کمپنی میسر آگئی تھی۔ اُنھوں نے مجھ سے جی بھر کے شاعری سُنی اور میں نے اُن سے فرمائش کر کر کے اپنے من پسند گانے سُنے اور پھر گانوں کے ساتھ رقص بھی دیکھا۔
زندگی کا سارا حُسن امرتسر کے کینال گیسٹ ہاﺅس کے ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ جیسے پرانی شراب کسی خوبصورت بوتل میں۔ اُس روز سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی ایک شخصیت تارا سنگھ سندھو نے ڈنر کے لےے Invite کیا تھا۔ سو شام کو ہم سب تیار ہو کر وہاں پہنچ گئے۔ گاڑیوں سے نیچے اُترتے ہی آتش بازی سے ہمارا سواگت کیا گیا۔ پھول برسائے گئے۔ ڈھول بجائے اور بھنگڑے ڈالے گئے۔ شادی کا سماں تھا۔
محبتیں اتنی کہ سمیٹنا مشکل تھا۔
میزبانوں کی حویلی بہت بڑی، خوبصورت اور کلچرڈ تھی۔
اُن کے دلوں کی طرح۔
جب سب مہمان کرسیوں پر بیٹھ گئے تو میزبان اور اُن کے بھائی تشریف لائے اور اُنھوں نے ایک ایک مہمان کے قدموں کو چھوا اور یہ جملہ ہر بار کہا۔
”آپ آئے بہار آئی“۔
میں نے کسی میزبان کو مہمانوں کی اتنی عزت افزائی کرتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اُس کے بعد ڈنر میں کونسا کھانا تھا جو نہیں تھا کونسا مشروب تھا جو پیش نہیں کیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نوکروں کو اجازت نہ تھی وہ خود اور اُن کے گھر والے خدمتگار تھے۔
سردار جی نے مہمانوں اور خاص کر مسلمانوں کو جی بھر کے گوشت کھانے کی درخواست کی اور ساتھ کھڑے ہوئے انڈین مسلم کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ہم نے خاص طور پر ان سے مُرغیاں اور بکرے ذبح کرائے ہیں تاکہ آپ حلال گوشت کے بارے میں شک و شبہ میں نہ رہیں۔
اُس کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی جو کئی دن سے سبزیاں اور دالیں کھا کھا کر کمزورہو گئے تھے۔ گوشت کی ڈشوں پر ٹوٹ پڑے ان میں زیادہ تر گوجرانوالہ، لاہور اور فیصل آباد کے تھے اس لےے میزبان صاحب کی توقعات پر پورے اُترے۔
کھانے کے بعد دارو ہی دارو اُوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف دارو ہی دارو، سب کے ہاتھ میں دارو، سب کی آنکھوں میں دارو، سب کی باتوں میں دارو، پینے والے پی رہے تھے، اور دیکھنے والے بس دیکھ رہے تھے ان میں کُچھ سکھ بھی شامل تھے۔ دارو جن کی فطرت سے میل نہ کھاتا تھا۔ یہ بھی فطری معاملہ لگتا ہے۔ مجھے بھی کافی سِکھوں نے منت سماجت کی مگر میں مضبوط رہا پھر ایک لڑکی میرے لےے دارو لے کر آئی اور کافی اصرار کیا تو میں نے اُس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا مجھے تو چڑھ بھی گئی۔
میری اس بات سے وہ سمجھ گئی کہ میں تو ”مومن بندہ“ ہوں۔
شرمائی اور چلی گئی۔
رات بہت بیت گئی تو ایک حیران کُن منظر دیکھنے کو ملا۔ جب ہمارے میزبان سردار جی نے اعلان کیا۔
”کہ آج تک ہماری بہو بیٹیوں نے اس طرح مہمانوں کے سامنے کبھی ڈانس نہیں کیا مگر آج ہم سب اتنے خوش ہیں کہ آپ سب کی آمد کی خوشی میں مِل کر بھنگڑے ڈالیں گے۔
پھر میوزک تھا۔
سکھنیاں تھیں۔
سکھ تھے۔
اور بھنگڑے تھے۔
بعد میں مہمان بھی اُن کے ساتھ شامل ہو گئے۔
کچھ صحافی بھی اس دعوت میں چپکے سے شریک ہو گئے۔
اور اگلے دن اس واقعے کو اخبارات میں خوب اُچھالا گیا۔
پتہ نہیں میزبان صاحب کا کیا بنا؟
—–٭٭٭—–
عجیب دُشمن تھے
میں نے امرتسر سے جو ”جپھی“ ڈالنے کا پروگرام بنایا تھا اور اس شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں گُم ہو جانے کی نیّت باندھی تھی۔ اُس کے خلاف ایک بھرپور سازش ہو گئی۔ دعوت ناموں کی بھرمار نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا۔ ”لیڈران“ کے لےے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ کس کے ناشتے، کس کے لنچ اور کس کے ڈنر کو عزت بخشی جائے۔ ہم کسی کا دِل نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ اس لےے گروپ بنا لےے گئے۔ کہیں سے دعوت نامہ ملتا تو ایک گروپ کو بھیج دیا جاتا دوسری جگہ دوسرے گروپ کو، دراصل میزبانوں کی محبت سے ہم ہار گئے تھے۔ ہمارے انکار سے اُن کے اصرار میں زیادہ کشش تھی اور یہ کشش ہمیں کھینچ لے جاتی۔
سکھوں کی فراخ دلی، میزبانی اور اتنی ساری محبتوں نے ہماری نظروں میں اُنھیں مشکوک بنا دیا تھا دِل کہتا تھا ضرور دال میں کُچھ کالا ہے۔
کُچھ نہ کُچھ ہو کے رہے گا۔
کیونکہ ہم ”دشمنوں کے درمیان شام“ ہی نہیں بلکہ صبح و شام گذار رہے تھے اور آنکھیں بند کیے اُن کا دیا ہوا پی رہے تھے، پکا ہوا کھا رہے تھے۔ حیران کُن امر یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے صحیح سلامت واپس آجاتے، رات کو کلمہ پڑھ کر سوتے مگر صبح تک زندہ ہوتے، آئینہ دیکھتے تو وہی شکل و صورت۔
عجیب دشمن تھے….
اجنبی دیس، اجنبی شہر اور اجنبی گھروں میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ ہم جہاں بھی گئے میزبانوں کا شوق اور انتظار دیکھنے والا تھا۔ وہ ہمیں اپنی بہو بیٹیوں میں یوں جا کر بٹھا دیتے جیسے ہم اُن کے فیملی ممبرز ہوں۔ کھانے کی ٹیبل پر زیادہ تر پاکستان اور خاص کر پنجاب کے بارے میں باتیں ہوتیں۔ مسلمانوں اور سکھوں کے لطیفے سُنائے جاتے خوب قہقہے لگتے، بھنگڑے ڈالے جاتے۔
میں جس انڈیا کا نقشہ آنکھوں میں لے کر آیا تھا یہ تو اُس سے بالکل مختلف تھا۔
یہ کیسے سردار تھے جو ہمارے پاﺅں چھوتے، ہمیں ”جپھیاں“ ڈالتے اور ہمارے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے اتنے معصوم، سادہ اور بھولے بھالے سردار ہم نے پہلی بار دیکھے تھے اس لےے یہ ہمیں نقلی سردار لگے۔
ہمارے ہاں بھی سردار ہوتے ہیں جن کے رُعب اور دبدبے سے وجاہت اور شباہت سے غرور اورگھمنڈ سے پتہ چلتا ہے یہ اصلی سردار ہیں۔
بالآخر ایک صبح قطار اندر قطار میزبانوں کی بے شمار دعوتیں، بے پناہ محبتیں اوربے حد خلوص ٹھکرا کر میں اپنے مُرشد، اپنے دِل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے امرتسر کی سڑکوں پر نکل پڑا۔
اک شک سا ہوا تھا کہ پُکارا ہے کسی نے
پھر چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا میں
اجنبی سڑکوں، اجنبی گلیوں اور اجنبی بازاروں میں، اجنبی بن کر گھومتا رہا۔ کسی مقام یا کسی جگہ سے آشنا ہونے کی کوشش نہیں کی۔
بے خبری سے کسی بھی چیز کو تجسّس بھری نظروں سے دیکھنا ایک ایسی کیفیت ہے جسے خود تو Enjoy کیا جا سکتا ہے کسی کے ساتھ Shareنہیں کیا جا سکتا۔
جس کا اپنا ایک حُسن ہوتا ہے کُچھ اچھا لگے نہ لگے مگر اُس کے بارے میں بغیر جانے اُس کو دیکھنے اور چھونے کا نشہ ہی الگ ہے۔
میں نے بھی یہاں عقل کو تنہا چھوڑ دیا تھا اور دِل کی اُنگلی پکڑ کر سیر کر رہا تھا۔
جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنا کُچھ جان کر یہ بے خبری آتی ہے۔
اسی بے خبری کی چھڑی کو ہاتھ میں پکڑ کر میں چلتا رہا۔ کوئی منظر آنکھوں کو اچھا لگتا تو آنکھیں بند کر کے اُس کو قید کر لیتا۔
ایک پارک کے کونے میں دو سردار گُھڑ سواروں کے بڑے بڑے مجسمے نظر آئے۔ کافی دیر تک اُنھیں دیکھتا رہا۔
یہ سکھوں کے گُرو تھے یا آزادی کے ہیرو اس بات سے بے نیاز ہو کر دیکھتا رہا۔
کافی دیر تک ایک پرانی عمارت کو حیران ہو کر دیکھتا رہا۔ اُس کے سیلن زدہ دیواروں، بوسیدہ کھڑکیوں اور خستہ حال دروازوں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔
ع ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش
ایک دیوار پر کُچھ لفظ گُر مکھی میں لکھے تھے میرے خیال میں یہ اُس گھر میں رہنے والے بچوں کے نام ہوں گے کیونکہ بچے اکثر دیواروں پر اپنا نام لکھ دیتے ہیں۔
جانے اُس گھر کے مکیں کس دیس پہنچے کیا ہوئے؟
رہ گئے دیوار پر لکھے ہوئے بچوں کے نام
مجھے اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر کے در و دیوار کو آخری بار حسرت بھری نظروں سے دیکھا تھا تو پورا گھر مجھے اپنے وجود کا حِصہ لگنے لگا تھا۔ جب آخری بار میں نے اُسے چھونے کی خواہش کی تھی تو میرے ہاتھ چپک گئے تھے میں نے اُسے اُٹھا کر اپنی پُشت پہ رکھ لیا تھا اب میں جہاں جاتا ہوں میرا گھر بھی میرے ساتھ ہوتا ہے۔
جہاں جائیں ان آنکھوں میں ہے بس دیوار و در اپنا
سفر میں بھی لےے پھرتے ہیں ہم تو ساتھ گھر اپنا
بارشوں کے موسم میں مجھے اپنا گھر بہت یاد آتا ہے۔ حالانکہ اب وہ گھر میرا نہیں رہا پھر بھی سوچتا ہوں اُس کی چھت ٹپک رہی ہوگی، آنگن میں پانی ٹھہر گیا ہوگا، کہیں دیواروں کو نقصان نہ پہنچے، بے ساختہ قدم اُس کی طرف اُٹھنے لگتے ہیں۔
یادیں تھیں دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی
اُس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے
جس شہر میں کوئی جاننے والا نہ ہو اُس میں بھی آوارہ گردی کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ امرتسر کی سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں گھومتے ہوئے میں ہر کسی کو دیکھتا رہا مگر کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ کوئی رستے میں جاننے والا نہیں ملا۔ کسی نے حال نہیں پوچھا اور یہ سب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔
پتہ نہیں کیوں؟
اچانک مجھے دور سے ڈھول کی آواز سُنائی دی اوربہت سے لوگ اپنی طرف آتے دکھائی دےے۔
قریب آئے تو پتہ چلا دولہا جی بارات لے کے چلے ہیں جو بھی تھا چلو اس بہانے کُچھ دیر نہیں بلکہ زیادہ دیر تک سکھوں اور سکھنیوں کا ڈانس دیکھنے کا ایک بار پھر موقع مِل گیا۔ آنکھیں تھک گئیں مگر وہ ناچ ناچ کر نہیں تھکے۔
عجیب مست قوم ہے۔
امرتسر کے لوگ بھی اہل لاہور کی طرح زندہ دِل ہیں۔ جس طرف اور جہاں جائیں، ہنستے مُسکراتے چہرے نظر آئیں گے۔ زندگی اپنے جوبن پر دکھائی دے گی۔
کُچھ فاصلے پر ریل کی پٹڑی تھی جو شہر سے گذر رہی تھی۔ پٹڑی کے پاس جا کر میرے قدم خود بخود رُک گئے۔ ریل کی پٹری تک جانا اورپھر لوٹ آنا میرے بچپن کی عادت ہے۔ یہ اُن دنوں کی بات ہے جب مجھے ریل گاڑی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اپنے شہر کے اُجاڑ ریلوے اسٹیشن پر آنے والی بھولی بھالی، معصوم اور سادہ سی پسنجر ٹرین سے مجھے کبھی خوف نہیں آیا۔ اُس کے کُکّڑ انجن (Steam Enjin) کے ساتھ لگے دو مفلوک الحال یتیم بچوں جیسے ڈبے دیکھ کر مجھے اُس کی حالت پر بہت ترس آتا۔ میرا دِل کرتا اس گاڑی کو اُٹھا کر اپنے گھر لے آﺅں۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے والد صاحب کے ساتھ جب میں پہلی بار کراچی جا رہا تھا تو سمہ سٹہ اسٹیشن پر لمبی لمبی، مسافروں سے کھچا کھچ بھری ٹرینیں دیکھیں تو پریشان ہو گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان ٹرینوں کے خوفناک حادثات کی خبروں نے دِل دہلا دیا اور ڈر کا سانپ میرے اندر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔
اپنے شہر کے اُجاڑ ریلوے اسٹیشن پر وہ سنڈی کی طرح رینگتی ہوئی آنے والی ٹرین جس کے آواز سے صحرا موسیقی سے بھر جاتا اور بھی اچھی لگنے لگی۔ کبھی کبھار میں یونہی بے مقصد اُس پر بیٹھ کر چلا جاتا تھا۔
جیسے ہم کسی دوست کے ساتھ سیر کے لےے جاتے ہیں۔
اچانک تیز رفتار ٹرین پٹری پر سے گذر نے لگی اور اُس کا سارا شور مجھے اپنے اندر سے آتا ہوا محسوس ہوا یوں لگا جیسے وہ میرے سر سے گذر رہی ہے۔
قریب ہی کسی شادی پر بجنے والے ڈھول کی آواز، ریل گاڑی گذرنے کا شور اور اس شور میں رضا علی عابدی کا یہ جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔
”جب سے ریل گاڑی ایجاد ہوئی ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو دور دور بیاہنے لگے ہیں“۔
میں اس جملے کے اندر چھپی ہوئی دُکھ کی لہر کو پلکوں پہ سجائے واپس لوٹ رہا تھا۔
دھیرے دھیرے اسٹیشن کو گاڑی چھوڑ رہی تھی
جب وہ کہنے آئی بائے ہاتھ میں پھول اُٹھائے
——٭٭٭——
”چُک دے پھٹے“
راجہ پورس کا میلہ شروع تھا وہی راجہ پورس جس نے سکندر کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
انڈین آرمی نے وہاں ایک گرینڈ میوزیکل شو اورمشاعرے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو رنگوں کی برسات میں نہا گئے۔ اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن دعوتِ سخن دے رہے تھے۔
سب رنگ تیز تھے کوئی بھی پھیکا نہ تھا۔ وہ رنگ کپڑوں کے تھے یا پگوں کے جھنڈیوں کے تھے یا بتیوں کے، پھولوں کے تھے یا جھولوں کے خلوص کے تھے یا محبت کے تھے۔ استقبال کا رنگ تو سب سے جُدا تھا اور کُچھ ایسا والہانہ کے ہمارے پاﺅں زمین پر نخوت سے نہیں پڑتے تھے۔
میڈیا کا لشکر اور انڈین آرمی کے افسر ہمیں سب سے پہلے اُس یادگار پر لے گئے جو اُنھوں نے 47ءمیں مرنے والے شہیدوں کے لےے تعمیر کی تھی۔ سنگِ سیاہ سے بنی ایک ہاتھ کی پانچ اُنگلیاں پنجاب کے پانچ دریاﺅں کا سِمبل ہیں۔ وہاں ایک شخص بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا کہ تقسیم کے وقت لاکھوں پنجابی قتل ہوئے۔ سکھ یا مسلمان نہیں لاکھوں پنجابی قتل ہوئے، یہ اُن کی یاد میں ہاتھ تعمیر کیا گیا ہے۔
کُچھ دیر پہلے جو پھول ہم پہ نچھاور کیے گئے تھے وہ اب بے رحم جوتوں تلے کُچلے گئے تھے۔ تقسیم کے وقت ہزاروں معصوم لوگ بھی اسی طرح کچلے گئے ہوں گے۔ اس خیال نے مجھے ُدکھی کر دیا تھا اور میں سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اُس بھیڑ اور ہنگامے سے نکل کر دور ایک بنچ پر جا کر بیٹھ گیا۔
کچھ ہی دیر میں فضا ”پاکستان، ہندوستان دوستی زندہ باد“ کے نعروں سے گونج اُٹھی۔ سازوں کی مدّہم لے تیز ہو گئی۔ بھنگڑے ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ میرے چہرے پر بھی خوشی پھیل گئی۔ میں نے مغرب میں غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا تو اُس کا چہرہ بھی سُرخ ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی اب اس خطہ میں امن کا خواہاں تھا۔
جیسے جیسے سورج شام کی چادر اپنے جسم پر لپیٹتا گیا ویسے ویسے برقی قمقموں کی جگمگاہٹ میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسٹیج اورپنڈال کو بہت منفرد اور خوبصورت انداز میں سنوارا گیا تھا۔ اسٹیج پر پاکستان اور ہندوستان کا نقشہ اس سلیقے اور مہارت سے بنایا گیا تھا کہ ہر اہم شہر کے سامنے ایک چراغ پڑا تھا۔ مختلف شاعروں، گلوکاروں، فن کاروں، مقررّین اور مہمانوں نے آنا تھا اور اسٹیج پر آکر اپنے شہر کا چراغ جلانا تھا۔
پنڈال میں کثیر تعداد میں انڈین آرمی کے جوان، آفیسر اور اُن کی فیملیز یہ شو دیکھنے آئی ہوئیں تھیں۔ میوزیکل شو شروع ہو چُکا تھا۔ کمپیئر ہر سنگر کو بُلانے سے پہلے باآواز بلند یہ جملہ ضرور کہتا:
”چُک دے پھٹے اج واج پاکستان تک جانی چاہو دی“۔
میں پاکستانی مہمانوں کے لےے مخصوص آرام دہ صوفوں پر جا کر بیٹھ گیا چونکہ شعراءسے سنگرز کی تعداد زیادہ تھی اس لےے دو تین گلوکاروں کے بعد ایک شاعر کی باری آتی لیکن اس Combination سے محفل کا حُسن دوبالا ہو گیا تھا۔ اسٹیج پر جو بھی جاتا پہلے اپنے شہر کے سامنے رکھا چراغ جلاتا اس طرح ہندوستان اور پاکستان کا نقشہ دھیرے دھیرے روشن ہوتا جا رہا تھا اور بہت پیارا منظر بن رہا تھا۔
وائے حسرت مجھے بہاولپور کے سامنے چراغ جلانے کا موقع میّسر نہ آیا بقول عطاءالحق قاسمی ہر بندے کے حِصے کے کُچھ بے وقوف ہوتے ہیں مگر ہمارے تو وفد کے حِصے میں ایک بیوقوف آیا ہوا تھا اور اُس نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہاں بھی وہ اپنا بے وزن کلام سُنانے کے لےے جب اسٹیج پر پہنچا تو سب شہروں کے چراغ جلا ڈالے۔
شاعر، سنگرز کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ یہاں صدیق ندیم، بشریٰ حزیں، عنایت اللہ عاجز، عابد گوندل، انجم سلیمی، افضل ساحر طارق گجر اور راقم نے اپنا کلام سُنایا جبکہ سمیرا شہزاد نے گایا اس کے علاوہ انڈیا کے کُچھ ”تک بند“ شاعر بھی تھے۔ افضل ساحر نے جھولتے اور جھومتے ہوئے پنجابی کی ایک نظم سُنا ڈالی اُس کو کافی داد ملی، نظم پر یا جھول جھول کے پڑھنے پر…. پتہ نہیں
حدِّ نگاہ تک پھیلی رنگ برنگی پگوں سے تھوڑا اوپر چاند بہت انہماک سے یہ شو دیکھ رہا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اُسے مخاطب کرتے ہوئے اپنی نظم ”چاند تم سے شکائتیں ہیں بہت“ سُنا دی۔ اُس کے بعد میں نے اپنی غزل جس کے دو شعر کُچھ اس طرح تھے۔
چلو ہم بھی محبت کر ہی لیں گے
اگر اُس کا ارادہ ہو گیا ہے
بچھڑنے کا اُسے بھی دُکھ ہے شاید
کہ اب تو وہ بھی آدھا ہو گیا ہے
سُنا کر جب اپنی نشت پر آکر بیٹھا تو ایک سردار جی میرے پاس آئے اور آکر داد و تحسین کے ڈھونگرے برسانے لگے کہہ رہے تھے واہ جی واہ! آپ نے ہم ہندوستانیوں کے دِل کی بات کی ہے۔
میں نے سر کُھجاتے ہوئے پوچھا؟
وہ کیسے؟
یہی کہ اگر پاکستان کا ارادہ دوستی کا ہو گیا ہے تو ہمیں بھی جنگ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہم بھی دوستی کر لیں گے۔ نیز علیٰحدہ مُلک بنانے کا اتنا دُکھ ہوا ہے کہ اب آپ بھی آدھے رہ گئے ہیں۔
سردار جی بڑی بے وقوفی سے میرے شعروں کی تشریح کر رہے تھے اور میں حیرت سے اُن کا مُنہ تک رہا تھا۔
یوں تو تمام سنگرز نے سماں باندھے رکھا۔ سب کا تعلق پنجاب سے تھا مگر ایک بچے نے جس کی عمر بمشکل دس سال ہو گی میلہ لوٹ لیا اُس کا اعتماد، آواز اور انداز بے مثل تھا۔
نیتو جی نے بھی بہت خوب گایا وہ پنجاب میں بہت مقبول تھیں وہ صحیح معنوں میں پنجاب کی جٹی تھیں۔ سُرخ گلابی چہرے پر موٹی موٹی نشیلی آنکھیں لمبا قد، بھرا بھرا جسم، قمیض لاچا اور پاﺅں میں تِلّے دار کُھسّہ اُس شام شمع ¿ محفل وہ تھیں۔ اُن کو دیکھے سے مُنہ پر رونق آجاتی۔ نیتو جی نے جب اسٹیج پر آکر گانا شروع کیا تو بیماروں کا حال خود بخود اچھا ہو گیا اور جو تندرست تھے اُن کی حالت دیکھنے والی تھی۔
ایک کینیڈا مقیم پنجابی بھی اس محفل میں مہمان تھا۔ وہ گورا چٹا، لمبا چوڑا گھبرو تھا۔ جب اظہارِ خیال کے لےے آیا تو اُس نے ایک گھنٹے تک پنجابیوں کے قصیدے پڑھے مثلاً:
پنجابی خوبصورت ہوتا ہے
پنجابی بہادر ہوتا ہے۔
پنجابی دُنیا میں سب سے زیادہ محنتی ہے۔
پنجابی غیرت مند ہوتا ہے۔
وغیرہ وغیرہ۔
پنڈال میں بیٹھے سبھی لوگوں نے اُس کے خیالات سے سو فیصد اتفاق کیا اور اُس کے قد جیسی لمبی تقریر بڑے ذوق و شوق سے سُنی ظاہر ہے اپنی تعریف کسے اچھی نہیں لگتی۔
تقریر کے اختتامی لمحات میں پاکستانی وفد کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا گیا شعراءکو ایک یادگاری شیلڈ پیش کی گئی اور اُس کے بعد ایک پُر تکلف ڈنر۔
یہاں ایک انڈین مُسلم سے مختصر سی ملاقات بھی ہوئی جس کا اہتمام سکھوں نے پہلے سے کر رکھا تھا۔ وہ قریبی دیہات میں رہنے والا ایک مفلوک الحال کسان تھا۔ جس کی حالت اُس کے حلیے سے ظاہر تھی۔ اُس کے بچوں کی تعلیم پرورش اور شادی تک کے تمام اخراجات اُس کے گاﺅں کے سکھوں نے برداشت کیے تھے۔ اُس کی آنکھیں اور باتیں مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اُس کی آنکھیں سکھوں کے لےے تشکر کے جذبوں سے بھری ہوئی تھیں اور وہ بات بات پر اُن کو دُعائیں دے رہا تھا۔ اُس کی حالت پاکستانیوں سے مِل کر ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ کوئی سُندر سپنا دیکھ رہا ہو۔ اس مُلاقات کا مقصد تو یہی تھا کہ ہمیں یہ تاث ¿ر دیا جائے کہ سکھ مسلمانوں کے لےے محبت، ہمدردی اور ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں۔
اللہ کرے ایسا ہی ہو۔
مجھے اُن کی یہ سرگرمی پسند آئی کیونکہ یہ دلوں کو قریب لانے والی تھی۔ یہ عمل ماضی کی نفرتوں کے شعلے بجھا کر حال کی محبتوں کے چراغ جلانے جیسا عمل تھا۔
بحیثیتِ پبلشر بھی میرا تعارف انڈین رائٹرز کے لےے بہت پُرکشش رہا۔ اس لےے میرے پاس اُن کی دی ہوئی کچھ کتابیں اکٹھی ہوگئیں، اور وہ بھی مختلف بھاشاﺅں میں۔
جس رائٹر کو پتہ چلتا پاکستان کے ایک پبلشر بھی اس وفد میں شامل ہیں تو وہ ڈھونڈ کر بڑی گرم جوشی سے آکر ملتا اور اپنی کتاب یا کتابیں عقیدت و محبت کے جذبات کے علاوہ اس خواہش کے ساتھ پیش کرتا کہ اگر یہ کتابیں ترجمہ ہو کر پاکستان سے شائع ہو جائیں تو ہزاروں میں فروخت ہوں، پبلشر تو لاکھوں کمائے مگر جذبہ ¿ خیر سگالی کے طور پر رائٹر رائلٹی نہیں لے گا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ میں بیٹھے بیٹھے اُن کے منوں احسان تلے دب جاتا۔ مجھے پتہ چلا کہ اسی طرح کی کاروائی پاکستانی رائٹرز بھی انڈین پبلشرز کو ڈالتے ہیں یہ بات سُن کر کُچھ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا کہ چلو حساب برابر ہو رہا ہے۔
اگلی صبح ہم دلی کےلئے روانہ ہو گئے۔
حسن عباسی