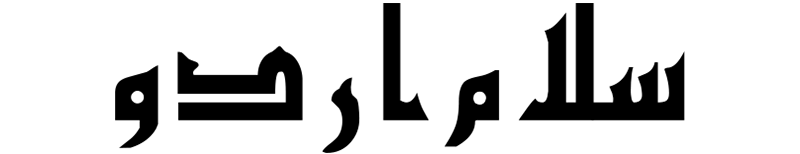نیلی ساڑھی
بمبئی: چونتیس کم عمر لڑکیاں تین قحبہ خانوں میں سے پچھلے ہفتے برآمد کی گئیں۔ ان میں سے تین کے چہرے کو ایذا پہچانے کے لیے تیزاب سے جلا دیا گیا تھا۔ پولیس نے پانچ عورتوں کو رنڈی خانوں کو چلانے اور طوائفوں کی آمدنی پر رہنے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ (ایک خبر)
حضور۔ میں سچ کہوں گی، سب سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گی۔ مگر وقت ہے آپ کے پاس اور آپ کے سماج کے پاس میری باتیں سننے کے لیے؟
میر انام سلیمہ ہے۔ میرے والد کا نام۔ خدا ان کی مغفرت کرے کریم بخش تھا۔ میرے والد کیا کرتے تھے۔ سچی بات یہ حضور کہ وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ کسی زمانے میں زمیندار تھے۔ بعد میں جب زمینوں پر سیلنگ لگی تو ان کے بدلے میں جو معاوضے کے کاغذات ملے ان کو بیچ کر کھاتے رہے۔
میری جائے پیدائش شکوہ آباد کی ہے۔
شکوہ آباد یوپی کا ایک قصبہ ہے۔ آگرے کا قصبہ کیا ہے پرانے کھنڈر جیسے مکانوں کا ایک مجموعہ ہے۔
انہیں میں سے ایک کھنڈر جیسے مکان میں میرا جنم ہوا تھا۔
میری ماں میری پیدائش کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں۔ میرے پیدا ہوتے ہی مر گئیں بیچاری۔ پھر میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔
میری سوتیلی ماں کا نام کریمن تھا۔ وہ ذات کی نائن تھی۔ مگر شکل و صورت کی ذرا اچھی تھی۔ جب ہی تو میرے والد نے بیوی کے مرنے کے دو مہینے بعد ہی اس سے نکاح پڑھوا لیا۔ محلے والے یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا معاملہ کریمن کے ساتھ پہلے سے چل رہا تھا۔
کریمن میری سوتیلی ماں ضرور تھی مگر ایمان کی بات یہ ہے حضور کہ اس نے کبھی سوتیلی ماں جیسا سلوک نہیں کیا مجھ سے۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس لیے مجھے اسکول پڑھنے بھیجا۔ وہ مجھے ہمیشہ سنیما ساتھ لے جاتی تھی اور ہر طرح کے ناز اٹھاتی تھی۔
جب تک میں پندرہ برس کی ہوئی تو سنیما کی پکی شوقین بن چکی تھی۔ سچ بات یہ ہے کہ شکوہ آباد جیسے مردہ قصبے میں اور کوئی تفریح کی جگہ بھی تو نہیں تھی۔ جب تک میں کوئی فلم دیکھتی رہتی تو ایسا لگتا کہ میں دوسری دنیا میں ہوں۔ ایک حسین رومانی دنیا جس میں سب مرد خوبصورت تھے۔ نہ صرف ہیرو بلکہ ویلن بھی۔۔۔ اور سب عورتیں اور لڑکیاں حسین تھیں اور سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فلموں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ حضور مگر خاص طور سے یہ سیکھا کہ اپنی زندگی کی کٹھنائیوں اور محرومیوں سے سنیما کے اندھیرے میں کیسے بچا جا سکتا ہے اور کچھ بھی سیکھا۔ مثلاً ہیروئن کی طرح کپڑے پہننا۔ ان کے جیسے بال بنوانا یا کٹوانا۔ اس زمانے میں میرا ما تھا بھی بڑا تھا اور فرنج یعنی کٹے ہوئے بالوں کی جھالر میرے چہرے پربھی اچھی لگتی تھی۔
اگلے دن ہی میرے خالہ زاد بھائی محمود علی نے جو مجھ سے عمر میں پانچ چھ برس بڑے ہوں گے، پہلی ہی جھلک میں پہچان لیا کہ میں نے ’’لو ان شملہ‘‘ دیکھ کر ہی اپنے بال کاٹے ہیں۔ اس لیے وہ ہلکے سے مذاق میں کہنے لگے ’’کیوں سلیمہ ’ لو ان شملہ‘ تو دیکھا ’لو ان شکوہ آباد‘ کے بارے میں کیا رائے ہے؟‘‘ اتنی بے شرمی کی بات سن کر میرا سارا چہرہ گلابی ہو گیا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دوں؟ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ محمود بھائی بھی دو چار پھبتیاں کس کر وہاں سے چلے گئے۔ ہاں جاتے جاتے اتنا کہہ گئے کہ وہ دو دن کے بعد علی گڑھ جا رہے ہیں۔ کسی کو سنیما چلنا ہو تو ان کے ساتھ وہ کل چل سکتا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا۔ میں کریمن کو اماں کہتی تھی ’’چلو گی اماں؟‘‘اماں نے کوئی بہانہ کر دیا۔ ابا تو سنیما جانے کو تیار نہیں تھے۔ اماں نے کہا ’’اپنے گھر کاہی تو لڑکا ہے تو اس کے ساتھ چلی جا۔ برقع اوڑھ کے‘‘۔
اگلے دن میں محمود بھائی کے ساتھ سنیما ہو لی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ بھی آخری دسمبر کی رات۔ کڑاکے کی سردی تھی۔ تانگے میں بیٹھی تو محمود بھائی پاس بیٹھے تھے۔ ان کا ہاتھ نہ جانے کس طرح میرے برقعے کے اندر آ گیا۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولے ’’افو تمہارے ہاتھ تو بالکل ٹھنڈے ہو رہے ہیں ‘ اور اپنے ہاتھوں کی گرمی مجھے پہنچاتے رہے۔ تھوڑی دیر میں میرے ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں کی طرح جلنے لگے۔
سنیما آ گیا تو وہ تانگے والے کو پیسے دے کر مجھے اندر ہال میں لے چلے۔ میں حیران رہ گئی۔ جب میں نے دیکھا انہوں نے ایک باکس ریزرو کر رکھا تھا۔ یہاں ہم دونوں اکیلے تھے۔ اس لیے فلم شروع ہونے پر محمود بھائی نے میرا برقع اتار دیا اور آہستہ آہستہ ان کا بازو میرے گرد حمائل ہو گیا۔ فلم کافی بکواس تھی مگر ہیرو ہیروئن کی محبت کے بہت سین تھے جو میرے لیے کافی دلچسپی رکھتے تھے۔
جو نکتے میری سمجھ میں نہیں آتے تھے، محمود بھائی کا ہاتھ میری تربیت کرتا رہا۔ ایک سین تھا جس میں ہیروئن گر پڑتی ہے۔ ہیرو گھبرا کر بھاگتا ہے اور زمین پر بیٹھ کر پوچھتا ہے۔
’’چوٹ لگی ہے؟‘‘
ہیروئن منہ بنا کر کہتی ہے ’’بہت لگی ہے‘‘۔
’’کہاں‘‘ ہیرو پوچھتا ہے۔
’’یہاں‘‘ وہ ٹخنے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیتی ہے۔ وہ ٹخنہ دبانے لگتا ہے۔
پھر وہ کہتی ہے ’’یہاں‘‘ اور گھٹنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
وہ گھٹنا دبانے لگتا ہے۔
پھر وہ کہتی ہے ’’نہیں۔ وہاں نہیں۔۔۔ یہاں‘‘
’’کہاں‘‘ وہ پوچھتا ہے۔
وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیتی ہے ’’یہاں‘‘۔
ہیرو کے ہاتھ بے اختیار سینے کی طرف بڑھتے ہیں۔۔۔ بڑھتے ہیں پھر ایک دم رک جاتے ہیں۔ مگر محمود بھائی کا ہاتھ نہیں رکا اور میں نے بھی لذت بھرے درد کو محسوس کر کے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں۔
اگلے دن تو محمود بھائی علی گڑھ چلے گئے اور میں ان کی یاد کو سینے سے لگائے اسکول چلی گئی۔ اسکول سے لوٹی تو دروازے پر ہی میں نے برقع اتارا اور اندر گھس رہی تھی کہ بندو سقے سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ وہ اندر سے خالی مشک کندھے پر لٹکائے باہر نکل رہا تھا اور میں اندر جا رہی تھی۔ ہم دونوں کا معانقہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ دو پل کے لیے ہم ایک دوسرے کے مقابل ٹھٹھک کر رہ گئے۔ میں نے دیکھا کہ سقے کا لونڈا مجھ سے ذرا ہی بڑا تھا اور جس کے ابھی مونچھیں بھی نہ نکلی تھیں، منہ پھاڑے میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ میں بھلا سقے کے لونڈے کو کب خاطر میں لانے لگی تھی۔ پھر بھی گھبراہٹ میں اس کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ پھر چوکنی ہو کر اندر چلی گئی اور یہ واقعہ دوپہر کے سناٹے میں کھویا رہا۔ کسی نے ہم کو دیکھا نہیں تھا لیکن نشہ حسن میں ڈوبی ہوئی میری خوشی کا کیا ٹھکانہ کہ کل محمود بھائی جس صورت پر مر مٹے تھے، آج اس صورت کو دیکھ کر ایک سانولا سلونا سقے کا لونڈا گھن چکر ہو گیا تھا۔
سقے کے لونڈے کو میں کب منہ لگانے والی تھی مگر مجھے یہ اچھا لگتا تھا کہ میرے حسن کے پجاریوں میں ایک کا اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب بھی مجھے موقع ملتا میں کسی نہ کسی بہانے سے بندو کے سامنے آ جاتی یا اسے اپنی ایک جھلک دکھا کر فوراً پردہ کر لیتی جیسے غلطی سے سامنا ہو گیا ہو۔ وہ بے چارہ تو یہ امید ہی کبھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ ایک شریف زادی سے چھیڑ چھاڑ کی پاداش میں ابا اسے مار مار کے ادھ موا نہ کر ڈالتے۔ مگر اس آنا کانی میں مجھے بڑا مزہ آتا۔ وہ مرے یا جیے مجھے کیا غرض؟
گرمیوں کی چھٹی میں محمود بھائی پھر شکوہ آباد آئے۔
کبھی خالہ اماں کے گھر جانے کے بہانے ہم ان کے ہاں ملتے۔ کبھی کچھ نہ کچھ بہانہ نکال کر وہ ہمارے ہاں آ جاتے۔ کبھی سنیما ہم اماں کو ساتھ لے کر چلے جاتے اور کبھی کبھی ہم خود ہی سنیما چلے جاتے۔ اس دن میں نیلی ساڑی پہنی، نیلا میرا محبوب رنگ تھا اور محمود کو بھی بے حد پسند تھا اور تب ’’باکس‘‘ میں بیٹھ کر ہی پکچر دیکھتے۔ بلکہ پکچر برائے نام ہی دیکھی جاتی۔
ایک بار وہ سقے کا لونڈا بندو ہمیں وہاں مل گیا اور میں نے محمود بھائی سے کہہ دیا کہ وہ بیچارہ میرا شکار ہو گیا ہے۔
’’بہت خوب‘‘ محمود بھائی بولے ’’تو شادی کر ڈالو‘‘۔
’’اس سے شادی کرے میری جوتی‘‘۔
’’پھرکس سے شادی کرو گی؟‘‘
’’آپ کو معلوم ہے‘‘۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل ہیروئن والے انداز میں کہا۔
’’پھر تو اماں سے بات کرنی ہی پڑے گی‘‘۔ وہ ہنس کر بولے۔
اور میں نے ان کے بازو میں گھس کر کچھ کھسرپھسر کی۔
’’سچ! پھر تو دیر نہیں کرنی چاہیے‘‘۔
’’ہاں محمود۔ ورنہ میں مر جاؤں گی‘‘۔
’’ارے مریں تمہارے دشمن‘‘۔
اس سے تیسرے دن محمود ہمارے گھر آیا اور ابا کو بیٹھک میں دیکھ کر اور اماں کو سوتا پا کر مجھ سے آہستہ سے بولے ’’اماں انکار کر رہی ہیں‘‘۔
’’کیوں؟ مجھ میں کیا برائی ہے؟‘‘
’’تم میں کچھ برائی نہیں ہے۔ مگر اماں کہتی ہیں خالہ کریمن نائی خاندان سے ہیں۔ سقے نائیوں میں پٹھان لوگ شادی کرنا نہیں چاہتے‘‘۔
’’سقے نائیوں کا ذکر کیوں کیا؟‘‘
’’آہستہ بولو! اماں اٹھ جائیں گی۔ سقوں میں شادی کرنے کے تم بھی خلاف ہو۔ ہونا؟‘‘
’’ہائے اللہ اب کیا ہو گا؟ مجھے تو ابھی سے ابکائیاں آنے لگی ہیں۔ نہ جانے کب بھانڈا پھوٹ جائے‘‘۔
’’فکر کیوں کرتی ہو میری جان؟ ہم تو ابھی نہیں مرے۔ بس دو چار دن انتظار کرو۔ پھر میں کوئی ترکیب نکالتا ہوں‘‘۔
اور وہ چلا گیا۔
اس کے بعد میں اس سے کبھی نہیں ملی تین دن بعد جب بندو پانی کی مشک ڈالنے آیا تو نظر بچا کر ایک لفافہ میرے پاس سے گزرتے ہوئے ڈال گیا۔ اس کی یہ ہمت؟ میں نے سوچا۔ مگر خط کے اوپر پتا محمود کی لکھائی میں تھا۔
میں نے اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے لفافہ کھولا۔ اندر بس تین سطریں تھیں۔
’’جان من۔ آج تم آدھی رات کے بعد کسی ٹرین سے آگرہ آ جاؤ‘‘۔
میں وہاں تمہیں ملوں گا۔ وہاں میں نے قاضی کا انتظام کر رکھا ہے۔
تمہارا محمود
نوٹ: ’’نیلی ساری پہننا‘‘
میں نے خط کو کئی بار پڑھا۔ بالکل ’’مسلم سوشل‘‘ کی فلمی سچویشن تھی۔ میں نے بھی ویسی ہی تیاری کی جیسی مسلم سوشل فلم کی ہیروئن کرتی ہے۔
دو تین جوڑے کپڑے نکالے جو میرے پاس بہترین تھے۔ کاٹن کی نیلی ساری رات کو پہننے کے لیے نکالی۔ جو زیور بھی میرے پاس تھے ان کو اٹیچی میں رکھا اور سردرد کا بہانہ کر کے سویرے ہی سے لیٹ رہی۔
گرمی کی راتیں تھیں اور چبوترے پر میرے والد اور والدہ سورہے تھے۔ میں نیچے صحن میں اپنے پلنگ پر پڑی تھی۔ پاس ہی بوڑھیا فتو اپنی کھاٹ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ہوش میں ہوتی بھی تو کیا کرتی۔ بیچاری بہری تھی اور آنکھوں میں موتیا بند اترا ہوا تھا۔ سو جب رات کے بارہ بجے تو میں چپکے سے اٹھی۔ کوٹھری میں جا کر نیلی ساری پہنی۔ برقع اوڑھا۔ اٹیچی کیس ہاتھ میں لیا اور (ننگے پاؤں جوتیاں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے) باہر نکل گئی۔
گلی کے موڑ پر پہنچی تھی کہ سامنے بندو کھڑا دکھائی دیا۔ یہ کمبخت یہاں اس وقت کیا کر رہا تھا؟ پاس گئی تو دیکھا کہ وہ تو میرے راستے میں اڑا کھڑا ہے۔ ’’بی بی جی۔ آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟‘‘
’’تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟‘‘
’’یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے خاندان کا نمک کھایا ہے۔ اس نمک کا حق پورا کر رہا ہوں۔ بی بی جی واپس چلی جائیے‘‘۔
میں برقع میں سے منہ نکالے دراتی ہوئی سیدھی چلی گئی۔ آخر وقت پر وہ راستے سے ہٹ گیا۔۔۔
’’بی بی جی۔۔۔ مت‘‘۔ وہ وہیں کھڑا تھا اس لیے اس کی آواز پوری نہ آئی۔۔۔
’’بی بی جی۔۔۔‘‘
’’بی بی۔۔۔‘‘
پھر وہ آواز جو شاید میرے ہی ضمیر کی آواز تھی۔ آنا بند ہو گئی۔
اسٹیشن پہنچ کر میں نے دو بجے والی گاڑی سے آگرہ کا ٹکٹ خریدا اور ایک زنانہ درجے میں بیٹھ گئی۔
آگرہ پر حسب وعدہ محمود میرا انتظار کر رہا ہو گا۔ انتظار کی گھڑیاں بھی کتنی دلچسپ ہوتی ہیں، وہاں وہ میرے انتظار میں اسٹیشن کی گھڑی دیکھ رہا ہو گا کہ چار بجیں اور گاڑی وہاں پہنچے۔ اور یہاں میں بھی اسی انتظار کا شکار ہوں اور چلتی ہوئی ٹرین کے بند شیشے میں سے مستقبل کی جھلکیاں مجھے نظر آ رہی تھیں۔
گاڑی آگرہ اسٹیشن پر پہنچتی ہے۔
چلتی ہی گاڑی میں سے میری نظریں دراز قامت محمود کو ڈھونڈھ نکالتی ہیں۔
’’محمود‘‘ میں آواز دیتی ہوں۔
وہ ہلکی ہوتی ہوئی ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگتا ہے۔ ڈنڈا پکڑ کر درجے میں گھس آتا ہے۔ سب لوگوں کے سامنے بھینچ کر مجھے گلے لگا لیتا ہے۔
’’سلیمہ! میری اچھی سلیمہ! تم آ گئیں نا؟‘‘
اس کی ایک دن کی بڑھی ہوئی داڑھی مجھے اپنے گالوں پر اچھی لگتی ہے۔
گاڑی ٹھہر جاتی ہے۔
وہ میرا اٹیچی کیس سنبھالتا ہے۔ مجھے پلیٹ فارم پر اتارتا ہے۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے کان میں کہتا ہے ’’قاضی جی۔ ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ پورے سو روپے کا وعدہ کیا ہے ان کو دوں گا اس بے وقت کی شادی کا‘‘۔
ہم ٹیکسی میں بیٹھے اور ٹیکسی گھڑ گھڑ کرتی ہوئی روانہ ہو گئی۔
رات کے دھندلکے میں شہر کی روشنیاں عجیب عجیب لگ رہی تھیں اور ٹیکسی ایسی چلتی ہے جیسے ریل چل رہی ہو۔ کیا لوہے کے پہیے لگے ہیں اس میں۔
ارے یہ سب تو میرا تخیل تھا۔ ابھی تو میں ٹرین ہی میں تھی اوراس کی گھڑگھڑاہٹ میرے کانوں میں۔ باہر آگے کے شہر کی دھندلی روشنیاں ہلکی ہوتی ہوئی ٹرین میں سے دکھائی دے رہی تھیں۔ اس بار ٹرین ایک جھٹکے کے ساتھ ٹھہر گئی۔
میں نے نیچے اترنے کے بعد پہلے جھانک کر دیکھا۔ مسافروں کی بھیڑ بھاڑ میں کوئی ترکی ٹوپی پہنے ہوئے دوسرے سروں کے اوپر سے جھانکتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ اترنے والے مسافر، چڑھنے والے مسافر، خونچے والے ریلوے بابو گھمسان کا عالم تھا۔ کوئی تعجب نہیں کہ اس بھیڑ میں کوئی کھو جائے۔
میں جان کر کھلے دروازے میں کھڑی رہی تاکہ میں خود بھیڑ میں نہ کھو جاؤں اور محمود کو دور سے دیکھ کر پہچان جاؤں۔ مگر ٹرین چلنے لگی اور محمود نہ آیا۔ میں چلتی گاڑی سے اتر گئی۔ اب پلیٹ فارم تقریباً خالی ہو چکا تھا۔
دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔۔۔
سوائے ایک پستہ قد آدمی کے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ جو شاید اسی طرح ہر اکیلی لڑکی کو گھور کر دیکھتا ہو گا۔ میں جلدی جلدی قدم بڑھاتی ہوئی زنانہ ویٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ سوچا محمود کو بھی شاید کہیں دیر لگ گئی ہو گی۔ چند منٹ میں آتا ہو گا۔ تب تک میں منہ ہاتھ دھو کرتا زہ دم ہو جاؤں۔
ویٹنگ روم سے باہر نکلی تو اسی پستہ قد آدمی کو گھورتے دیکھا۔ وہ میلی سی پتلون پر ایک دھاری دار بش شرٹ پہنے تھا۔ اب وہ میری طرف بڑھا۔
میں ادھر ادھر دیکھ کر واپس جانے والی تھی کہ وہ آدمی بولا ’’سنیے‘‘ میں ٹھٹھک کر رک گئی۔ سوچا شاید محمود نے اسے مجھے لانے کے لیے بھیجا ہو۔
’’آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟‘‘
’’جی ہاں‘‘
’’کس کا؟‘‘
’’محمود علی صاحب کا۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟‘‘
’’نہیں تو۔ میں انہیں نہیں جانتا۔ میں تو بومبے فلم کمپنی سے ادھر فلم اسٹار کے قابل لڑکے اور لڑکیاں کھوجنے آیا ہوں۔۔۔ آپ دیکھنے میں قبول صورت دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے سوچا شاید آپ کو دلچسپی ہو؟‘‘
’’جی نہیں۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے محمود علی صاحب سے ملنے سے۔ اگر کوئی لمبے سے صاحب کسی لڑکی کو ڈھونڈنے آئیں تو آپ مہربانی کر کے انہیں ادھر بھیج دیجئے‘‘ یہ کہا اور میں اندر چلی گئی۔
وہ آدمی سگریٹ جلا کر سامنے ٹہلنے لگا۔
میں نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں مگر فلم اسٹار بننے میں کسے دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے سوچا ممکن ہے یہ آدمی جھوٹا ہو۔۔۔ یا ممکن ہے سچ بولتا ہو۔ محمود آئے گا تواس سے مشورہ کروں گی۔ مگر صبح سے شام ہوئی اور محمود نہیں آیا۔
میں نے وہیں کھانا منگوا کر کھایا۔
اب میں نے سوچا کسی وجہ سے علی گڑھ جانا پڑا ہو گا محمود کو۔ ممکن ہے یونیورسٹی کھل گئی ہو۔ سو میں رات کی گاڑی سے علی گڑھ کے لیے روانہ ہو گئی۔
مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ یا شاید نہیں ہوا کہ وہ پستہ قد آدمی بھی اسی گاڑی میں سوار ہوا۔ مگر پھر اس نے مجھ سے کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کی۔ علی گڑھ کے اسٹیشن پر میں اتری۔ مجھے تعجب ہوا، یا شاید نہیں ہوا کہ وہ آدمی بھی اترا۔ رات کا وقت تھا۔ میں ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھ گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ محمود کے ہوسٹل کا پتہ میرے پاس موجود تھا۔ صبح ہوتے ہی میں ایک سائیکل رکشہ پر سوار ہو کر وہاں پہنچی۔ یونیورسٹی سنسان پڑی تھی۔ اس کے کمرے میں اکثر کمروں کی طرح قفل لگا ہوا تھا۔
مگر برابر کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔
اس میں سے چک ہٹا کر ایک نوجوان باہر نکلا۔ مجھے دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں۔
’’آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں شاید؟‘‘
’’ہاں اپنے کزن محمود علی خاں صاحب کو‘‘۔
’’محمود کی کزن ہیں آپ؟ پڑوسی ہونے کے ناطے میرا فرض ہے آپ کی سیوا کروں۔ وہ تو ابھی واپس نہیں آیا۔ میں ہی اکیلا ہوسٹل میں ہوں۔ میرا کمرہ حاضر ہے۔ رکشا والے کو رخصت کیے دیتا ہوں‘‘۔
نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کی چمک مجھے اچھی نہیں لگی اور میں ’’جی نہیں شکریہ‘‘ کہہ کر برآمدے سے اتر کر رکشا میں آ کر بیٹھ گئی۔
’’چلو واپس، اسٹیشن‘‘۔
جب واپس پہنچی تو اس پستہ قد آدمی کو ٹہلتے ہوئے پایا۔ شام کر ٹرین سے میں شکوہ آباد چلی آئی۔ رات کو پہنچی۔ وہ آدمی بھی اسی ٹرین میں سوار ہوا۔ مگر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔
رات کو شکوہ آباد پہنچ کرتا نگے پر سوار ہو کر میں نے گلی کے نکڑ پر تانگہ کو رکوایا کیونکہ اب پیسے میرے پاس ختم ہو گئے تھے۔
سوچا گھر جا کر ماں باپ سے کہوں گی۔ کسی سہیلی کے ہاں گئی تھی اور ان سے تانگے کا کرایہ دلوا دوں گی۔ مگر ڈیوڑھی تک ہی پہنچی تھی کہ ارادہ بدل گیا۔
اندر سے ابا اور کریمن بوا کی آوازیں آ رہی تھیں۔
’’اس لڑکی کو کبھی سوتیلی بیٹی نہیں سمجھا۔ اپنی بیٹی سے بڑھ کر پالا اور یہ ہمارے خاندان کی ناک کٹوا کر بمبئی چلی گئی فلم اسٹار بننے‘‘۔
’’ہاں بھئی۔ تو میں سنیما دیکھنے کو اسی لیے منع کرتا تھا۔ محمود کہتا تھا کہ کب سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اس سے کہتی تھی دونوں ساتھ چلیں گے۔ تم ہیرو بننا۔ میں ہیروئن بنوں گی۔ مگر وہ شریف کا بچہ ہے۔ اس نے منع کر دیا تو کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے اب!‘‘
’’دو چار مہینوں میں ٹھوکریں کھا کر آ جائے گی، اپنے چہیتے باپ کے پاس‘‘۔
’’کیا منہ لے کر آئے گی۔ اب آئی تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی۔۔۔‘‘
میں یہیں تک سن پائی تھی کہ مجھے فوراً تانگے کا خیال آیا۔ دبے پیروں وہاں سے لوٹی۔
’’واپس اسٹیشن چلو‘‘ تانگے والے سے کہا۔
مگر راستے بھر سوچتی گئی کہ پیسا کیسے ادا کروں گی۔ شاید کوئی زیور گروی رکھنا پڑے۔ مگر اس وقت رات کو گروی کون رکھے گا؟
مجھے تعجب ہو۔۔۔ یا شاید نہیں ہوا۔۔۔ کہ پستہ قد آدمی اسٹیشن کے باہر ہی ٹہل رہا تھا۔ اس نے تانگہ رکتے ہیں اس کا کرایہ چکا دیا۔
’’آپ نے اچھا کیا وقت پر آ گئیں۔ متھرا کی گاڑی آنے والی ہے۔ وہاں سے فرنٹیئر میل پکڑنی ہے ہمیں‘‘۔
اس نے میرا ٹکٹ نہیں خریدا۔ اس کے پاس میرا ٹکٹ پہلے سے موجود تھا۔ گاڑی آنے سے پہلے صرف اتنا کہا ’’آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ زنانے ڈبے میں آپ سفر کریں گی۔ آپ کو کمپنی والوں کے سپرد کرتے ہی میں تو کلکتہ چلا جاؤں گا۔۔۔ کچھ بنگالی چہرے بھی لانے ہیں‘‘۔
وہ اپنے قول کا پکا نکلا۔
مجھے زنانے درجے میں سوار کرا کے خود مردانے درجے میں بیٹھ گیا۔ جب گاڑی کسی بڑے اسٹیشن پر رکتی تھی تو چائے اور کھانے کو پوچھنے آ جاتا تھا۔
اور ہاں ایک بار بہت سے فلمی پرچے مجھے دے گیا اور کہنے لگا ’’اب دیکھیے، اگلے مہینے ان سب میں آپ کی تصویریں چھپیں گی‘‘۔ اور میں نے سوچا محمود ان سب پرچوں کو پڑھتا ہے دیکھ کر کتنا جلے گا۔
میں نے اٹیچی کیس کو تکیہ بنا کر برقع رات کو اوڑھ لیا۔ لیکن بمبئی پہنچتے پہنچتے اب وہ غیر ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے اسے وہیں ٹرین کے ڈبے میں چھوڑ دیا۔
بمبئی پہنچ کر اس نے مجھے ٹیکسی میں بٹھایا۔ خود ڈرائیور کے پاس بیٹھا اور کہا ’’میرین ڈرائیو چلو‘‘۔
’’کیا کمپنی کا دفتر وہاں ہے؟‘‘
’’ہاں یہی سمجھو۔ اسٹوڈیو تو ہمارا دادر میں ہے۔ یہ سیٹھانی جی کا فلیٹ ہے۔ وہ تمہیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہیں ’’۔
’’تمہاری کمپنی کی مالکن عورت ہے؟‘‘
’’ہاں۔ جب ہی تو ہم جب کسی لڑکی کو لے کر آتے ہیں توراستے بھر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے‘‘۔
’’کیا نام ہے تمہاری سیٹھانی کا؟‘‘
’’مس للیتا کماری۔ پہلے وہ بھی ہیروئن ہوتی تھیں مگر کسی اور نام سے کام کرتی تھیں۔ اب ذرا موٹی ہو گئی ہیں، سوکمپنی کھول لی ہے‘‘۔
فلیٹ کے دروازے پر بورڈ لگا ہوا تھا ’’مس للیتا کماری۔ فلم پروڈیوسر‘‘۔
مگر میں نے دیکھا ایک جنگلہ بھی لگا ہوا ہے۔ دروازے کے باہر گیلری میں جسے ایک چوکیدار نے کھولا اور پھر بند کر دیا۔ قفل لگا دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب تو ہوا مگر میرے پستہ قد ساتھی نے اطمینان دلا دیا۔ ’’سیٹھانی جی بہت وہمی ہیں۔ ہمیشہ چوروں سے ڈرتی ہیں۔ کوئی ان کے ہیرے جواہرات چرا کر نہ لے جائے‘‘۔
ایک بڑھیا روم میں لے جا کر بٹھا یا گیا۔
پستہ قد آدمی برابر کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بند کر لیا۔
نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پرکھ رہا ہے۔ مگر کمرہ خالی تھا کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔
کچھ ہی دیر بعد دروازہ پھر کھلا اور وہی پستہ قد آدمی ایک موٹی عورت کے ساتھ داخل ہوا جو کسی زمانے میں بہت خوبصورت رہی ہو گی۔
’’اچھا نیلی ساری‘‘۔
’’جی۔ اچھا گڈ بائی اور گڈ لک‘‘۔
اور یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔
اور سیٹھانی میری طرف آئیں۔ مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
بڑے پیار سے میرے سر کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ’’ابھی تو تم تھکی ہوئی ہو کچھ کھا پی کر آرام کرو۔ رات کو تمہارا ٹیسٹ لیں گے۔ مجھے یقین ہے تم کامیاب ہو گی اور للیتا کماری کا نام روشن کرو گی‘‘۔
یہ کہہ کر انہوں نے تالی بجائی۔
ایک نوکرانی ایک ٹرے میں کچھ مٹھائی اور دودھ کا گلاس لے کر آئی۔
’’کھاؤ پیو‘‘۔
’’آپ نہیں کھائیں گی؟‘‘
’’نہیں۔ میں ابھی کھا پی کر اٹھی ہوں۔ یہ سب تمہارے لیے ہے‘‘۔
یہ کہہ کر انہوں نے مٹھائی کی ایک ڈلی میرے منہ میں ڈال دی۔ کہنے لگیں کہ یہ شگون کی مٹھائی ہے۔ مٹھائی کا مزہ تو اچھا تھا مگر اس میں کچھ کڑواہٹ ملی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا پستہ و بادام شاید کڑوا ہو گا۔
پھر انہوں نے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھایا۔
’’پیو میری جان‘‘ انہوں نے بڑے پیارسے دودھ اپنے ہاتھ سے پلایا۔ دودھ خوشبو دار تھا۔ گلاب کی سی خوشبو تھی۔ مگر ساتھ میں ہلکی سی کڑواہٹ بھی تھی۔ سیٹھانی نے اپنا ہاتھ نہ ہٹایا جب تک میں نے دودھ کا گلاس ختم کر لیا اور پھر ان کی آواز ایک دوسری دنیا سے آئی ’’اور بھول جاؤ سب کچھ۔ اب تمہاری نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔۔۔‘‘
ایک لامتناہی رات میں ایک ڈراؤنا خواب دیکھتی رہی۔
دیکھتی ہوں کہ ایک ہاتھ میرے باپ نے پکڑا ہوا ہے۔ دوسرا ہاتھ میری سوتیلی ماں نے۔
ایک ٹانگ محمود نے پکڑی ہوئی ہے۔
دوسری ٹانگ اس پستہ قد آدمی نے جو مجھے بمبئی لایا تھا۔
اور سیٹھانی کی نگرانی میں میرے بدن میں یہ لمبے لمبے آگ کے سوئے گھپوئے جا رہے ہیں۔
اور میرے بدن میں سے سارا خون پانی بن کر نکل رہا ہے۔
نہ جانے کتنی دیر یہ خواب دیکھتی رہی۔
اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں ایک گدے دار پلنگ پر پڑی تھی۔
میرے سرکے نیچے ایک مخملی تکیہ تھا۔
جب میں نے اپنی ٹھوڑی کھجانے کے لیے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ٹانگ سکوڑنی چاہی تو ٹانگ بھی پائے سے بندھی ہوئی ہے۔ دوسری ٹانگ بھی۔ سربھی۔ اسی طرح کسی چین سے باندھا گیا ہے کہ میں صرف سامنے سے دیکھ سکتی ہوں اور پیراہن کے بغیر آرام دہ سولی پر چڑھا دی گئی ہوں۔
اتنے میں سیٹھانی میرے سامنے کھڑی تھی۔
کہنے لگی ’’عیش و آرام کرو گی یا تکلیف اٹھاؤ گئی اس کا فیصلہ تم پر ہے؟ دیر یا سویر سب رام ہو جاتی ہیں۔ تم بھی ہو جاؤ گی۔ مگر ابھی یا کچھ اور دیر کے بعد؟‘‘
’’میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی؟‘‘
’’میں چاہتی ہوں اس خوبصورت بدن کو انسانیت کو آرام پہچانے کے لیے استعمال کرو۔ جو مجرد ہیں ان کے لیے ایک رات کی بیوی بنو۔ جو اپنی بیویوں کی بدصورتی سے بھاگے ہوئے ہیں ان کے بدن کو تسکین پہنچاؤ۔ جو سیاسی، سماجی، اقتصادی ذمہ داریوں میں دبے ہوئے ہیں ان کا دل بہلا کر ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ ہمارے سماج کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں‘‘۔
’’تم چاہتی ہو کہ میں رنڈی بن جاؤں‘‘۔ میں نے سوال سیٹھانی سے کیا اور اپنے آپ سے بھی ’’ارے میں ماں بننے والی ہوں۔ ماں!‘‘
’’تم کبھی نہیں بنو گی۔ اس بار بھی نہیں۔ کسی بار بھی نہیں۔ دیکھنا چاہتی ہو یہ آپریشن کس نے کیا ہے؟ اور بغیر کسی لوہے کے آلے کے؟‘‘
اتنے میں اس کے اشارے پر ایک کے بعد ایک آدمی آتا گیا اور میرے پائنتی کھڑا ہو کر میری نگاہ کے دائرے سے اوجھل ہوتا گیا۔
ہندو، مسلمان، سکھ، کرسچین، پوربی بھیا، مدراسی۔
نہ جانے کہاں کہاں سے یہ مسٹنڈے اکٹھے کیے گئے تھے۔۔۔
اب مجھ میں چیخنے چلانے کی طاقت نہیں تھی۔ میرا کلیجہ منہ کو آیا اور ایک ابکائی کے بعد میں نے قے کر دی اور بے ہوش ہو گئی۔
جب پھر ہوش آیا تو میری باقاعدہ ٹریننگ شروع ہوئی۔
ایک بار حکم کی خلاف ورزی کی سزا میں کوڑے پڑے تھے اور کھانا بند۔
دو بار حکم کی خلاف ورزی کی سزا میں منہ کالا کرانا تھا۔
تین بار حکم کی خلاف ورزی کی سزا ایسڈ منہ پر پھینکنا تھا۔ اس کا مظاہرہ میرے سامنے ایک معصوم بلی پر کر دیا گیا تھا جو ایسڈ سے جل کر لوٹ پوٹ کر وہیں میرے سامنے ڈھیر ہو گئی۔
میں نے ایک درخواست کی کہ مجھے یہ بتا دو کہ اس پستہ قد آدمی نے مجھے پہچانا کیسے کہ یہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ جواب ملا ’’تمہاری نیلی ساری سے۔ تمہارے عاشق نے دو سو روپے لے کر یہ اطلاع دی تھی کہ اس ٹرین سے تم آؤ گی اور یہ کپڑے پہنے ہو گی‘‘۔
یہ سننے کے بعد میں تیار ہو گئی۔ اب رہ ہی کیا گیا تھا۔
اگر میں بتاؤں کہ اگلے چھ برس تک کیا ہوا تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔
میرے گاہکوں میں کون نہیں تھا؟
افسر، بڑے بڑے بیوپاری، راجا، مہاراجا، نواب، فلم اسٹار، فلم پروڈیوسر، پہلے میرے ساتھ ایک آدمی جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھ پر بھروسا ہونے لگا۔ پھر مجھے جو روپیہ ملتا تھا اس میں سے ایک تہائی اپنے پاس رکھنے کی اجازت مل گئی۔
میں اپنا پرانا نام بھول گئی۔ نیا نام ہی کافی تھا۔ ’’نیلی ساری‘‘ میرے پاس ہر شیڈ کی نیلی ساریاں تھیں۔ شیفون کی نیلی ساری۔ کنجی ورم کی نیلی ساری۔ جارجٹ کی نیلی ساری۔۔۔ اور سوٹ کیس کے سب سے نیچے کاٹن کی نیلی ساری۔
ایک دن مجھے چھٹی تھی۔ (جمعہ کو یہ چھٹی میں ضرور لیا کرتی تھی)
اس دن نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے جوہو جانے کی سوجھی اور نہ جانے کیوں میں نے وہی پرانی کاٹن کی نیلی ساری پہنی۔ جوہو پہنچ کر میں نے ناریل کا پانی پیا۔ بھیل پوری کھائی۔ کوئی مجھے جانتا نہیں تھا اور میں اپنی گمنامی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ادھر ادھر گھومتی رہی۔
ایک جگہ ایک آدمی ریت کے پتلے بنا رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی پھیلی ہوئی چادر میں بیس پیسے پھینک دئیے۔ اس کے آگے کو بڑھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ زمین سے دو الٹی ٹانگیں اگ آئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی بے چارے کو الٹا زمین میں گاڑا گیا ہے۔ پاس ہی چادر پھیلائے ایک آدمی پیسے اکٹھا کر رہا ہے۔ میں نے اسے ایک روپیہ دیا اور پوچھا یہ آدمی کب نکلے گا۔ اس نے کہا سورج چھپتے اسے یہاں سے نکالوں گا۔ ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر برسوں تپسیا کی ہے تب جا کر یہ کمال حاصل کر پایا ہے کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سردے کر دن بھر الٹا لٹکا رہتا ہے۔
مجھے نہ جانے کیا سوجھی کہ سورج جب سمندرمیں ڈوبنے لگا تو پھر وہاں پہنچ گئی۔
وہ ڈھونگی ڈھول بجا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا، ’’دیکھو، دیکھو دنیا کا سب سے بڑا کمال۔ بارہ گھنٹے ریت میں دفن رہ کر آدمی زندہ ہو رہا ہے۔۔۔‘‘
ٹانگوں میں حرکت پیدا ہو رہی تھی اور پھر وہ آدمی جو ایک نیکر پہنے ہوئے تھا۔ نکل آیا اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو اپنی آنکھوں میں سے ریت نکال رہا تھا۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ پیسے کھنا کھن گر رہے تھے۔ اور میں منہ پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ جیسے سچ مچ کوئی مردہ زندہ ہو گیا ہو اور میں ایک معجزہ دیکھ رہی ہوں کیونکہ میرے سامنے شکوہ آباد کا وہ سقے کا لونڈا کھڑا تھا، بندو۔
تالیاں بجنی بند ہو گئیں۔
لوگ امڈتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ بندو اور اس کا ساتھی پیسے بٹورنے لگے۔ آدھے اس آدمی نے لیے آدھے بندو نے۔ پھراس آدمی نے کہا ’’اچھا بے میں چلتا ہوں۔ کل یہ تماشا چوپاٹی پر جمائیں گے‘‘۔
یہ کہا اور وہ چلتا بنا۔
اور میں وہیں کھڑی بندو کو دیکھتی رہی۔ وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔
پھر وہ آگے بڑھ کر میری طرف دیکھتا رہا۔
میں نے کہا ’’بندو‘‘۔
اس نے کہا ’’جی بی بی جی‘‘۔
’’تم شکوہ آباد سے کب آئے؟‘‘
’’چھ سال ہو گئے‘‘۔
’’سب خیریت ہے؟‘‘
اس کے چہرے سے پتا چلتا تھا کہ سب خیریت نہیں ہے۔
’’ابا تو خیریت سے ہیں؟‘‘ میں نے کرید کر پوچھا۔
’’ابا تو جنت کو سدھارے‘‘۔
میں نے دل ہی دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔
’’یہاں کہاں رہتا ہے؟‘‘
اس نے کہا ’’مہا لکشمی کے پاس ایک جھونپڑی میں‘‘۔
’’مجھے وہاں لے جا سکتا ہے؟‘‘
’’بی بی جی۔۔۔‘‘ اس کا چہرہ خوشی اور تعجب سے پھٹا کا پھٹا رہ گیا۔
’’تمہاری بی بی ساتھ رہتی ہے کیا؟‘‘
’’بی بی جی میری شادی نہیں ہوئی‘‘۔
’’پھر تو ٹھیک ہے۔۔۔ میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں‘‘۔
اس کا حال تو یہ تھا کہ شادی مرگ نہ ہو جائے۔
’’چلیے بی بی جی‘‘۔
’’چلو‘‘
سوہم مہا لکشمی والی جھونپڑی میں آ گئے۔ جھونپڑی ان پائیوں سے اچھی تھی جو سڑک کنارے پھیلے ہوئے تھے اور جن میں بے گھر لوگ آباد ہو گئے تھے۔ اور وہ لوگ ان سے اچھے تھے جو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر سونے کے لیے مجبور تھے۔ جھونپڑی میں ایک ٹوٹی پھوٹی کھٹیا تھی۔ میں اس پر ایسی سوئی جیسے دنیا کی خبر نہ ہو۔ چھ سال کے بعد میں سچ مچ کی چھٹی منا رہی تھی۔
صبح کو میں نے دیکھا بندو جھونپڑی کے باہر سورہا تھا۔
میں نے اسے اٹھایا۔
اندر آیا پوچھا ’’مجھے تو بہت اچھی نیند آئی۔ تم بھی اندر کیوں نہیں آ گئے؟‘‘
’’بی بی جی۔ اندر توا یک ہی چارپائی تھی اور آپ اس پر ایسی تھکی ہاری سورہی تھیں جیسے ایک بچہ سورہا ہو‘‘۔
’’مجھے تو ساتھ سونے کی عادت ہے۔ تم ہی آ جاتے‘‘۔
’’بی بی جی۔‘‘
’’نام بتاؤں دو چار کے؟ اور میں بتانے ہی لگی تھی۔ مگر اس نے اتنی لجاجت سے ’’بی بی جی‘‘ کہا کہ میں چپ رہ گئی۔
پھر وہ کہنے لگا۔ ’’قاضی جی جب نکاح پڑھا دیں گے تب ٹھیک ہے‘‘۔
’’قاضی جی!‘‘ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔
’’قاضی جی!‘‘ میں ہنستی رہی۔
اس کے چہرے پر ایسا بھولا پن تھا کہ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔
’’کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں پچھلے چھ برس سے کیا کرتی رہی ہوں؟‘‘
’’بی بی جی۔ میں نہیں جاننا چاہتا‘‘۔
’’۔۔۔ کہ ایک ایک رات میں۔۔۔‘‘
’’بی بی جی۔ خدا کے لیے چپ رہیے۔ میں نہیں جاننا چاہتا۔۔۔ قاضی جی نکاح پڑھا دیں گے پھر جو جی چاہے مجھے بتا دینا‘‘۔
’’قاضی جی‘‘ اور مجھے پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا اور میرے منہ سے نکل گیا ’’کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایک سقے کے لونڈے سے بیاہ کروں گی؟‘‘
یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور باہر چلا گیا۔
دو گھنٹے کے بعد کھانے کی چیزیں لے کر آیا اور میرے سامنے رکھ دیں۔ بغیر ایک لفظ کہے اپنا کھانا باہر لے گیا اور وہاں ہی کھایا۔
میراجی تو اکیلے کھانے کو نہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی جب بھوک لگی تو زہر مار کر لیا۔ سپہر کو وہ آیا اور کہنے لگا ’’میں جا رہا ہوں۔ تم جھونپڑی کا دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ میرے آنے تک کسی کے لیے نہ کھولنا‘‘۔
’’تم کہاں جاؤ گے؟‘‘
’’روزی کمانے‘‘۔
’’سر ریت میں دے کر الٹے لٹکنے کو تم روزی کمانا کہتے ہو‘‘۔
میں جانتی تھی وہ کیا جواب دے گا۔ میں اس جواب کو سننا چاہتی تھی کہ وہ کہے کہ ہر آدمی کو اپنے اپنے ڈھنگ سے روزی کمانا پڑتی ہے۔ کوئی ریت میں سر دیتا ہے کوئی۔۔۔ مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور چلا گیا۔
میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کھٹیا پر لیٹی رہی۔
تھوڑی دیر میں باہر سے سیٹیاں سنائی دینے لگیں۔
میں نے ایسی سیٹیاں پچھلے چھ برس میں بہت سنی تھیں۔ میں ان کا مطلب خوب سمجھتی تھی۔ دو ایک نے دروازے پر ٹھک ٹھک بھی کی لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ پرانی لکڑی کا دروازہ جو رسی سے بندھا ہوا تھا لات مار کر توڑ دے اور اندر چلا آئے۔ غریب بھی برائی کرتے ہیں اور امیر بھی۔ مگر غریب کی برائی میں امیروں کی سی بے حیائی نہیں ہوتی۔
وہ رات کو دیر میں آیا اور کچھ کھانا ساتھ لایا۔
میں نے کہا ’’کیا ہوا؟‘‘
اس نے کہا ’’وہی جو تم نے دیکھا تھا۔ شاید تمہارے آنے کی برکت ہے‘‘۔
’’برکت!‘‘ میرے جی میں آیا کہ کہوں کچوکے کیوں دیتے ہو۔ مگر اس نے ایسے بھولے پن سے کہا تھا کہ میں چپ رہی۔
اس رات میں سوچتی رہی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا کر رہی ہوں۔ چھٹی پر ہوں چھ برس ہو گئے محنت کرتے کرتے کچھ دن تو چھٹی کروں۔۔۔ یہاں جھونپڑی میں کون مجھے ڈھونڈنے آئے گا؟
بندو روز دو تین بجے جاتا اور رات گئے آتا۔
نہ میں اس سے پوچھتی کیا ہوا؟
نہ وہ مجھ سے پوچھتا کہ میں نے کیا کیا۔
نہ ہی اس نے پہلے دن کے بعد کبھی قاضی جی کی بات چھیڑی۔
وہ اپنے میلے کچیلے بسترکاڈھیر لیتا اور باہر جا کر بچھا دیتا۔ مگر وہ میرے لیے نئی دری، نئی چادر، نیا تکیہ لے آیا تھا۔ کھٹیا کو بھی ٹھوک پیٹ کر ٹھیک کر لیا تھا۔
میں اس کھٹیا پر اکیلی سوتی تھی۔
وہ باہر فٹ پاتھ پر اکیلا سوتا تھا۔
اس طرح تین ہفتے بیت گئے۔
میری پڑوس میں دو تین عورتوں سے دوستی ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور میں بمبئی میں نوکری ڈھونڈنے آئی تھی۔ یہاں آ کر بندو سقے سے ملاقات ہو گئی تھی۔ جس نے اپنی جھونپڑی میں پناہ دی تھی۔ جھوٹ بولنے کی مجھے عادت ہو گئی تھی۔
پھر ایک دن اسے آنے میں دیر ہوئی تو میں نے سوچا کہ ’’آج اس سے کہوں گی کہ تم یہ کام چھوڑ دو‘‘۔ وہ کہے گا ’’روزی کمانے کا ایک ہی ذریعہ آتا ہے مجھے‘‘۔
میں کہوں گی ’’مجھے بھی روزی کمانے کا ایک ہی ذریعہ آتا ہے۔ مگر میں چھوڑنے کو تیار ہوں‘‘۔
پھر وہ کہے گا ’’قاضی جی کو بلا لاؤں‘‘۔
مگر وہ اس رات نہ آیا۔
اگلے دن نہ آیا۔
تیسرے دن نہ آیا۔
میں نے پڑوسی عورتوں سے کہا۔ انہوں نے اپنے مردوں سے کہا۔ انہوں نے کہا وہ معلوم کریں گے۔ اس آدمی سے پوچھیں گے جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔
رات کو ایک آدمی ان میں سے آیا اور کہنے لگا،
’’بندو تو جیل میں ہے‘‘۔
’’جیل میں! کیوں کیا کیا اس نے؟‘‘
’’ریت میں دفن ہونا خود کشی کے برابر ہے۔ سپاہی کو ہفتہ نہیں کھلایا اس لیے وہ آتم ہتیا کے جرم میں پکڑ لے گیا۔ دوسرا آدمی بھاگ گیا۔ اب بندو جیل میں ہے۔ ضمانت پر ہی باہر آ سکتا ہے‘‘۔
’’کتنی ضمانت دینی ہو گئی؟‘‘
’’دو ہزار روپے‘‘۔ اس آدمی نے کہا جیسے دو لاکھ روپے ہوں۔ مگر میں نے سوچا۔ اس سے کہیں زیادہ تو میں نے بچا کر رکھے ہیں۔ شاید پانچ چھ ہزار تو ہوں گے۔ مگر وہ تو پیڈر روڈ والے فلیٹ میں ہیں۔ (ہماری جائے رہائش بدلتی رہتی تھی)
میں اسی شام کو پیڈر روڈ والے فلیٹ میں پہنچی۔ مجھے دیکھتے ہی للیتا کماری آگ بگولہ ہو گئی۔
’’میں تو سمجھی تھی تو مر گئی یا کوئی بھگا کر لے گیا تجھے‘‘۔
میں نے آواز کو قابو میں کرتے ہوئے کہا ’’میں جا رہی ہوں۔ اپنا روپیہ لینے آئی ہوں‘‘۔
یہ کہہ کر میں اندر اپنے کمرے میں گئی اور اپنا سوٹ کیس کھول کر روپے اور اپنا زیور نکالا۔ یہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک مسٹنڈا پیچھے کھڑا ہے ہاتھوں پر لمبے لمبے کالے ربڑ کے دستانے چڑھائے ہوئے۔ ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں مجھے معلوم تھا تیزاب رہتا ہے۔
’’کیا کر رہی ہے حرام زادی؟‘‘
چھ سال کے بعد آج نہ جانے کہاں سے مجھ میں ہمت آ گئی۔ میں بولی ’’اپنا روپیہ اور زیور لے جا رہی ہوں اور دیکھتی ہوں، کون مجھے روکتا ہے؟‘‘
اس بدمعاش نے اپنے سڑے ہوئے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا ’’تو جاؤ میری جان‘‘۔
اور جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے میرے منہ پر تیزاب کا وار کیا۔
جانتی تھی تیزاب کا اثر کیا ہو گا۔ میں دو ایک عورتوں کو دیکھ چکی تھی جو اپنا گلا سڑا چہرہ لیے اپنی زندگی کے آخری دن اس چکلے میں گزار رہی تھیں کیونکہ کہیں اور وہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئی تھیں، مگر میں تو مرنے کے لیے ہی تیار تھی کیوں نہ اس ظالم کو بھی ساتھ لیتی جاؤں۔ میں نے اپنے چہرے کی ناقابل برداشت اذیت کے باوجود اس کے ہاتھ سے بوتل چھین کر اس کے سرپر دے ماری۔ بوتل ٹوٹ گئی اور آدھا تیزاب جو اس میں تھا وہ اس آدمی کے چہرے پر گر پڑا۔ ایک غضب کی چیخ اس کے منہ سے نکلی اور اس چیخ کا نکلنا تھا کہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں بھی تیزاب گر گیا اور وہ آدمی پھر نہ چیخ سکا۔
میرا منہ جل رہا تھا۔ پھنک رہا تھا۔ مگر وہ روپیہ اور زیورات بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ اسے لے کر میں باہر آئی تو دیکھا کہ پولیس کی ریڈ ہوئی ہے۔ للیتا کماری بڑے ٹھسے سے صوفے پر بیٹھی پولیس انسپکٹر سے بات کر رہی تھی۔ ’’انسپکٹر صاحب میری تو ڈانس کلاس کی ابھی چھٹی ہے۔ اس لیے لڑکیاں اپنے اپنے گھر جا رہی ہیں۔۔۔ آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔۔۔ کیا منگاؤں آپ کے لیے۔۔۔ ٹھنڈا یا گرم۔۔۔؟
’’انسپکٹر صاحب‘‘۔
اب میں ان کے سامنے کھڑی تھی اور تیزاب میرے منہ پر بہہ رہا تھا اور میرے گوشت کے لوتھڑے لٹک رہے تھے۔ ’’اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔۔۔ یا شاید مر جاؤں۔ میں ایک بیان دینا چاہتی ہوں‘‘۔
بس حضور یہی سب کہا تھا اس بیان میں میں نے۔ میرا چہرہ جس پر پٹیاں بندھی ہیں اب اس قابل نہیں ہے کہ آپ دیکھیں لیکن ایک زمانہ تھا لوگ اس چہرے کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ بس مجھے یہی کہنا ہے آپ سے۔۔۔ اب اجازت دیجئے۔
بندو میرا انتظار کر رہا ہے۔
وہی ایک آدمی ہے جو انسان کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ اس چہرے کے پیچھے جو روح ہے اس کو دیکھتا ہے اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے کیونکہ قاضی صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔
٭٭٭
خواجہ احمد عباس