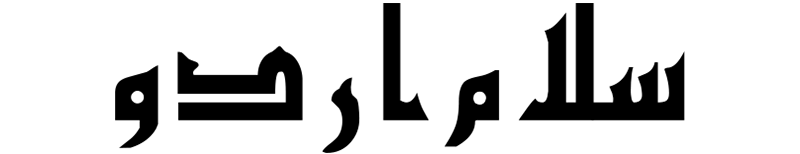انقلاب پسند
میری اور سلیم کی دوستی کو پانچ سال کا عرصہ گُزر چکا ہے۔ اس زمانے میں ہم نے ایک ہی سکول سے دسویں جماعت کا امتحان پاس کیا، ایک ہی کالج میں داخل ہُوئے اور ایک ہی ساتھ ایف۔ اے۔ کے امتحان میں شامل ہو کر فیل ہوئے۔ پھر پرانا کالج چھوڑ کر ایک نئے کالج میں داخل ہُوئے۔ اس سال میں تو پاس ہو گیا۔ مگر سلیم سُوئے قسمت سے پھر فیل ہو گیا۔ سلیم کی دوبارہ ناکامیابی سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ آوارہ مزاج اور نالائق ہے۔ یہ بالکل افترا ہے۔ سلیم کا بغلی دوست ہونے کی حیثیت سے میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ کہ سلیم کا دماغ بہت روشن ہے۔ اگر وہ کالج کی پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ دیتا۔ تو کوئی وجہ نہ تھی۔ کہ وہ صوبہ بھر میں اول نہ رہتا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے پڑھائی کی طرف کیوں توجہ نہ دی؟ جہاں تک میرا ذہن کام دیتا ہے مجھے اُس کی تمام تر وجہ، وہ خیالات معلوم ہوتے ہیں جو ایک عرصے سے اُس کے دل و دماغ پر آہستہ آہستہ چھا رہے تھے؟ دسویں جماعت اور کالج میں داخل ہوتے وقت سلیم کا دماغ ان تمام اُلجھنوں سے آزاد تھا۔ جنھوں نے اسے ان دنوں پاگل خانے کی چاردیواری میں قید کر رکھا ہے۔ ایام کالج میں وہ دیگر طلبہ کی طرح کھیل کود میں حصہ لیا کرتا تھا۔ سب لڑکوں میں ہر دلعزیز تھا۔ مگر یکایک اس کے والد کی ناگہانی موت نے اس کے متبسّم چہرے پر غم کی نقاب اوڑھا دی۔ اب کھیل کود کی جگہ غور و فکر نے لے لی۔ وہ کیا خیالات تھے، جو سلیم کے مضطرب دماغ میں پیدا ہُوئے؟۔ یہ مجھے معلوم نہیں۔ سلیم کی نفسیات کا مطالعہ کرنا بہت اہم کام ہے۔ اس کے علاوہ وہ خود اپنی دلی آواز سے نا آشنا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ گفتگو کرتے وقت یا یونہی سیر کرتے ہُوئے اچانک میرا بازو پکڑ کر کہا ہے۔
’’عباس جی چاہتا ہے کہ۔۔۔۔۔۔۔ ‘‘
’’ہاں۔ ہاں۔ کیا جی چاہتا ہے۔ میں نے اس کی طرف تمام توجہ مبذول کرکے پوچھا ہے۔ مگر میرے اس استفسار پر اس کے چہرے کی غیر معمولی تبدیلی اور گلے میں سانس کے تصادم نے صاف طور پر ظاہر کیا کہ وہ اپنے دلی مدّعا کو خود نہ پہچانتے ہُوئے الفاظ میں صاف طور پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جو اپنے احساسات کو کسی شکل میں پیش کر کے دوسرے ذہن پر منتقل کر سکتا ہے۔ وہ دراصل اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی قدرت کا مالک ہے۔ اور وہ شخص جو محسوس کرتا ہے۔ مگر اپنے احساس کو خود آپ اچھی طرح نہیں سمجھتا۔ اور پھر اس اضطراب کو بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اس شخص کے مترادف ہے۔ جو اپنے حلق میں ٹھنسی ہُوئی چیز کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مگر وہ گلے سے نیچے اُترتی چلی جا رہی ہو۔ یہ ایک ذہنی عذاب ہے۔ جس کی تفصیل لفظوں میں نہیں آ سکتی۔ سلیم شروع ہی سے اپنی آواز سے نا آشنا رہا ہے۔ اور ہوتا بھی کیونکر جب اس کے سینے میں خیالات کا ایک ہجوم چھایا رہتا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ بیٹھا بیٹھا اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور کمرے میں چکر لگا کر لمبے لمبے سانس بھرنے شروع کر دیے۔ غالباً وہ اپنے اندرونی انتشار سے تنگ آ کر ان خیالات کو جو اس کے سینے میں بھاپ کے مانند چکر لگا رہے ہوتے۔ سانسوں کے ذریعے باہر نکالنے کا کوشاں ہوا کرتا تھا۔ اضطراب کے انہی نکلیف دہ لمحات میں اس نے اکثر اوقات مجھ سے مخاطب ہو کر کہا
’’عباس! یہ خاکی کشتی کسی روز تُند موجوں کی تاب نہ لا کر چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ۔۔۔۔۔۔۔‘‘
وہ اپنے اندیشے کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتا تھا۔ سلیم کسی متوقع حادثے کا منتظر ضرور تھا۔ مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ حادثہ کس شکل میں پردہ ظہور پر نمودار ہو گا۔ اس کی نگاہیں ایک عرصے سے دُھندلے خیالات کی صورت میں ایک موہوم سایہ دیکھ رہی تھیں۔ جو اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس تاریک شکل کے پردے میں کیا نہاں ہے۔ میں نے سلیم کی نفسیات سمجھنے کی بہت کوشش کی ہے۔ مگر مجھے اس کی مُنقلب عادات کے ہوتے ہوئے کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کن گہرائیوں میں غوطہ زن ہے۔ اور وہ اس دنیا میں رہ کر اپنے مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ جب کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ ہر قسم کے سرمائے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ میں ایک عرصے سے سلیم کو مُنقلب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی عادات دن بدن بدل رہی تھیں۔ کل کا کھلنڈر الڑکا، میرا ہم جماعت ایک مُفکر میں تبدیل ہو رہا تھا۔ یہ تبدیلی میرے لیے سخت باعث حیرت تھی۔ کچھ عرصے سے سلیم کی طبیعت پر ایک غیر معمولی سکون چھا گیا تھا۔ جب دیکھو اپنے گھر میں خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اور اپنے بھاری سر کو گھٹنوں میں تھامے کچھ سوچ رہا ہے۔ وہ کیا سوچ رہا ہوتا۔ یہ میری طرح خود اسے بھی معلوم نہ تھا۔ ان لمحات میں میں نے اسے اکثر اوقات اپنی گرم آنکھوں پر دوات کا آہنی ڈھکنا یا گلاس کا بیرونی حصّہ پھیرتے دیکھا ہے۔ شاید وہ اس عمل سے اپنی آنکھوں کی حرارت کم کرنا چاہتا تھا۔ سلیم نے کالج چھوڑتے ہی غیر ملکی مصنفّوں کی بھاری بھرکم تصانیف کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ شروع شروع میں مجھے اس کی میز پر ایک کتاب نظر آئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس الماری میں جس میں وہ شطرنج۔ تاش اور اسی قسم کی دیگر کھیلیں رکھا کرتا تھا۔ کتابیں ہی کتابیں نظر آنے لگیں۔ اس کے علاوہ وہ کئی کئی دنوں تک گھر سے کہیں باہر چلا جایا کرتا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے سلیم کی طبیعت کا غیر معمولی سکون ان کتابوں کے انتھک مطالعہ کا نتیجہ تھا۔ جو اس نے بڑے قرینے سے الماری میں سجا رکھی تھیں۔ سلیم کا عزیز ترین دوست ہونے کی حیثیت میں مَیں اس کی طبیعت کے غیر معمولی سکون سے سخت پریشان تھا۔ مجھے اندیشہ تھا۔ کہ یہ سکون کسی وحشت خیز طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے سلیم کی صحت کا بھی خیال تھا۔ وہ پہلے ہی بہت کمزور جثّے کا واقع ہوا تھا۔ اس پر اس نے خوامخواہ اپنے آپ کو خدا معلوم کن کن الجھنوں میں پھنسا لیا تھا۔ سلیم کی عمر بمشکل بیس سال کی ہو گی۔ مگر اس کی آنکھوں کے نیچے شب بیداری کی وجہ سے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ پیشانی جو اس سے قبل بالکل ہموار تھی اب اس پر کئی شکن پڑے رہتے تھے۔ جو اس کی ذہنی پریشانی کو ظاہر کرتے تھے۔ چہرہ جو کچھ عرصہ پہلے بہت شگفتہ ہوا کرتا تھا۔ اب اس پر ناک اور لب کے درمیان گہری لکیریں پڑ گئی تھیں۔ جنہوں نے سلیم کو قبل ازوقت معّمر بنا دیا تھا۔ اس غیر معمولی تبدیلی کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتے دیکھاہے۔ جو مجھے ایک شعبدے سے کم معلوم نہیں ہوتی۔ یہ کیا تعجب کی بات ہے۔ کہ میری عمر کا لڑکا میری نظروں کے سامنے بوڑھا ہو جائے۔ سلیم پاگل خانے میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ وہ سڑی اور دیوانہ ہے۔ اسے غالباً اس بنا پر پاگل خانے بھیجا گیا ہے کہ وہ بازاروں میں بلند بانگ تقریریں کرتا ہے۔ راہ گذروں کو پکڑ پکڑ کر انہیں زندگی کے مشکل مسائل بتا کر جواب طلب کرتا ہے۔ اور امرا کے حریر پوش بچوں کا لباس اتار کر ننگے بچوں کو پہنا دیتا ہے۔ ممکن ہے۔ یہ حرکات ڈاکٹروں کے نزدیک دیوانگی کی علامتیں ہوں۔ مگر میں یقین کے ساتھ کَہ سکتا ہوں کہ سلیم پاگل نہیں ہے۔ بلکہ وہ لوگ جنھوں نے اسے امن عامہ میں خلل ڈالنے والا تصور کرتے ہوئے آہنی سلاخوں کے پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ کسی دیوانے حیوان سے کم نہیں ہیں! اگر وہ اپنی غیر مربوط تقریر کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ تو کیا ان کا فرض نہیں کہ وہ اس کے ہر لفظ کو غور سے سنیں؟ اگر وہ راہ گذروں کے ساتھ فلسفہ ءِ حیات پر تبادلہ ءِ خیالات کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا اس کے یہ معنی لیے جائیں گے کہ اس کا وجود مجلسی دائرہ کے لیے نقصان دہ ہے؟۔ کیا زندگی کے حقیقی معنی سے باخبر ہونا ہر انسان کا فرض نہیں ہے؟ اگر وہ متمول اشخاص کے بچوں کا لباس اُتار کر غربا کے برہنہ بچوں کا تن ڈھانپنا چاہتا ہے تو کیا یہ عمل اُن افراد کو اُن کے فرائض سے آگاہ نہیں کرتا جو فلک بوس عمارتوں میں دوسرے لوگوں کے بل بوتے پر آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ننگوں کی ستر پوشی کرنا ایسا فعل ہے کہ اسے دیوانگی پر محمول کیا جائے؟ سلیم ہر گز پاگل نہیں ہے۔ مگر مجھے یہ تسلیم ہے کہ اس کے افکار نے اسے بے خود ضروربنا رکھا ہے۔ دراصل وہ دُنیا کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہے۔ مگر دے نہیں سکتا ایک کم سن بچے کی طرح وہ تُتلا تُتلا کر اپنے قلبی احساسات بیان کرنا چاہتا ہے۔ مگر الفاظ اسکی زبان پر آتے ہی بکھر جاتے ہیں۔ وہ اس سے قبل ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔ مگر اب اسے اور اذیت میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ پہلے ہی سے اپنے افکار کی الجھنوں میں گرفتار ہے۔ اور اب اسے زندان نما کوٹھڑی میں قید کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میں نے آج تک سلیم کی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں دیکھی۔ جس سے میں یہ نتیجہ نکال سکوں۔ کہ وہ دیوانہ ہے۔ ہاں البتہ کچھ عرصے سے میں اس کے ذہنی انقلابات کا مشاہدہ ضرور کرتا رہا ہوں۔ شروع شروع میں جب میں نے اس کے کمرے کے تمام فرنیچر کو اپنی اپنی جگہ سے ہٹا ہُوا پایا تو میں نے اس تبدیلی کی طرف خاص توجہ نہ دی دراصل میں نے اس وقت جو خیال کیا۔ کہ شاید سلیم نے فرنیچر کی موجودہ جگہ کو زیادہ موزوں خیال کیا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ میری نظروں کو جو کرسیوں اور میزوں کو کئی سالوں سے ایک جگہ دیکھنے کی عادی تھیں۔ وہ غیر متوقع تبدیلی بہت بھلی معلوم ہوئی۔ اس واقعے کے چند روز بعد جب میں کالج سے فارغ ہو کر سلیم کے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فلمی ممثلوں کی دو تصاویر جو ایک عرصے سے کمرے کی دیواروں پر آویزاں تھیں اور جنھیں میں اور سلیم نے بہت مشکل کے بعد فراہم کیا تھا۔ باہر ٹوکری میں پھٹی پڑی ہیں اور ان کی جگہ انہی چوکھٹوں میں مختلف مصنفّوں کی تصویریں لٹک رہی ہیں۔ چونکہ میں خود ان تصاویر کا اتنا مشتاق نہ تھا۔ اس لیے مجھے سلیم کا یہ انخلاب بہت پسند آیا۔ چنانچہ ہم اس روز دیر تک ان تصویروں کے متعلق گفتگو بھی کرتے رہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس واقعہ کے بعد سلیم کے کمرے میں ایک ماہ تک کوئی خاص قابل ذکر تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ مگر اس عرصے کے بعد میں نے ایک روز اچانک کمرے میں بڑا سا تخت پڑا پایا۔ جس پر سلیم نے کپڑا بچھا کر کتابیں چُن رکھیں تھیں اور آپ قریب ہی زمین پر ایک تکیہ کا سہارا لیے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ میں یہ دیکھ کر سخت متعجّب ہوا۔ اور کمرے میں داخل ہوتے ہی سلیم سے یہ سوال کیا۔ کیوں میاں! اس تخت کے کیا معنی؟ سلیم جیسا کہ اس کی عادت تھی مسکرایا اور کہنے لگا۔
’’کرسیوں پر روزانہ بیٹھتے بیٹھتے طبیعت اُکتا گئی ہے۔ اب یہ فرش والا سلسلہ ہی رہے گا۔ بات معقول تھی۔ میں چپ رہا۔ واقعی روزانہ ایک ہی چیز کا استعمال کرتے کرتے طبیعت ضرور اچاٹ ہو جایا کرتی ہے۔ مگر جب پندرہ بیس روز کے بعد میں نے وہ تخت مع تکیے کے غائب پایا۔ تو میرے تعجّب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اور مجھے شُبہ سا ہوا کہ کہیں میرا دوست واقعی خبطی تو نہیں ہو گیا ہے۔ سلیم سخت گرم مزاج واقع ہُوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے وزنی افکار نے اسے معمول سے زیادہ چڑ چڑا بنا رکھا تھا۔ اس لیے میں عموماً اس سے ایسے سوالات نہیں کیا کرتا۔ جو اس کے دماغی توازن کو درہم برہم کر دیں یا جن سے وہ خوامخواہ کھج جائے۔ فرنیچر کی تبدیلی، تصویروں کا انخلاب، تخت کی آمد اور پھر اس کا غائب ہو جانا واقعی کسی حد تک تعجب خیز ضرور ہیں اور واجب تھا کہ میں ان اُمور کی وجہ دریافت کرتا۔ مگر چونکہ مجھے سلیم کو آزردہ خاطر کرنا، اور اس کے کام میں دخل دینا منظور نہ تھا۔ اس لیے میں خاموش رہا۔ تھوڑے عرصے کے بعد سلیم کے کمرے میں ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی تبدیلی دیکھنا میرا معمول ہو گیا۔ اگر آج کمرے میں تخت موجود ہے۔ تو ہفتے کے بعد وہاں سے اُٹھا دیا گیا ہے۔ اس کے دو روز بعد وہ میز جو کچھ عرصہ پہلے کمرے کے دائیں طرف پڑی تھی۔ رات رات میں وہاں سے اٹھا کر دوسری طرف رکھ دی گئی ہے۔ انگیٹھی پر رکھی ہُوئی تصاویر کے زاویے بدلے جا رہے ہیں۔ کپڑے لٹکانے کی کھونٹیاں ایک جگہ سے اُکھیڑ کر دوسری جگہ پر جڑ دی گئی ہیں۔ کرسیوں کے رُخ تبدیل کیے گئے ہیں۔ گویا کمرے کی ہر شے ایک قسم کی قواعد کرائی جاتی تھی۔ ایک روز جب میں نے کمرے کے تمام فرنیچر کو مخالف رخ میں پایا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ اور میں نے سلیم سے دریافت کر ہی لیا۔
’’سلیم میں ایک عرصے سے اس کمرے کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا دیکھ رہا ہوں۔ آخر بتاؤ تو سہی یہ تمہارا کوئی نیا فلسفہ ہے۔ ؟‘‘
’’تم جانتے نہیں ہو، میں انقلاب پسند ہوں‘‘
سلیم نے جواب دیا۔ یہ سن کر میں اور بھی متعجب ہوا۔ اگر سلیم نے یہ الفاظ اپنی حسبِ معمول مسکراہٹ کے ساتھ کہے ہوتے تو میں یقینی طور پر یہ خیال کرتا کہ وہ صرف مذاق کر رہا ہے۔ مگر یہ جواب دیتے وقت اس کا چہرہ اس امر کا شاہد تھا، کہ وہ سنجیدہ ہے۔ اور میرے سوال کا جواب وہ اِنہی الفاظ میں دینا چاہتا ہے لیکن پھر بھی میں تذبذب کی حالت میں تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا۔
’’مذاق کر رہے ہو یار؟‘‘
’’تمہاری قسم بہت بڑا انقلاب پسند‘‘
یہ کہتے ہوئے وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد اس نے ایسی گفتگوشروع کی تھی۔ مگر ہم دونوں کسی اور موضوع پر اظہار خیالات کرنے لگ گئے تھے۔ یہ سلیم کی عادت ہے کہ وہ بہت سی باتوں کو دلچسپ گفتگو کے پردے میں چُھپا لیا کرتا ہے۔ ان دنوں جب کبھی میں سلیم کے جواب پر غور کرتا ہُوں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سلیم درحقیقت انقلاب پسند واقع ہُوا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ کسی سلطنت کا تختہ اُلٹنے کے درپے ہے۔ یا وہ دیگر انقلاب پسندوں کی طرح چوراہوں میں بم پھینک کر دہشت پھیلاناچاہتا ہے۔ بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے۔ وہ ہر چیز میں انقلاب دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نظریں اپنے کمرے میں پڑی ہوئی اشیا کو ایک ہی جگہ پر نہ دیکھ سکتی تھیں۔ ممکن ہے میرا یہ قیافہ کس حد تک غلط ہو۔ مگر میں یہ وثوق سے کَہ سکتا ہوں کہ اس کی جستجو کسی ایسے انقلاب کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جس کے آثار اس کے کمرے کی روزانہ تبدیلیوں سے ظاہر ہیں۔ بادی النظر میں کمرے کی اشیا کو روز الٹ پلٹ کرتے رہنا دیوانگی کے مترادف ہے۔ لیکن اگر سلیم کی ان بے معنی حرکات کا عمیق مطالعہ کیا جائے تو یہ امر روشن ہو جائیگا کہ ان کے پسِ پردہ ایک ایسی قوت کام کر رہی تھی۔ جس سے وہ خود ناآشنا تھا۔ اسی قوت نے جسے میں ذہنی تعصب کا نام دیتا ہوں۔ سلیم کے دماغ میں تلاطم بپا کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس طوفان کی تاب نہ لا کر ازخود رفتہ ہو گیا۔ اور پاگل خانے کی چاردیواری میں قید کر دیا گیا۔ پاگل خانے جانے سے کچھ روز پہلے سلیم مجھے اچانک شہر کے ایک ہوٹل میں چائے پیتا ہوا ملا۔ میں اور وہ دونوں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ گئے۔ اس لیے کہ میں اُس سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بازار کے چند دکان داروں سے سنا تھا کہ اب سلیم ہوٹلوں میں پاگلوں کی طرح تقریریں کرتا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اس سے فوراً مل کر اُسے اس قسم کی حرکات کرنے سے منع کر دوں۔ اس کے علاوہ یہ اندیشہ تھا کہ شاید وہ کہیں سچ مچ نحبوط القواس ہی نہ ہو گیا ہو۔ چونکہ میں اس سے فوراً ہی بات کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے ہوٹل میں گفتگو کرنا مناسب سمجھا۔ کرسی پر بیٹھتے وقت میں غور سے سلیم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے اس طرح گھورتے دیکھ کر سخت متعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا۔۔۔۔۔۔
’’شاید میں سلیم نہیں ہوں۔ ‘‘
آواز میں کس قدر درد تھا۔ گو یہ جُملہ آپ کی نظروں میں بالکل سادہ معلوم ہو۔ مگر خدا گواہ ہے میری آنکھیں بے اختیار نمناک ہو گئیں۔ ” شاید میں سلیم نہیں ہُوں‘‘
گویا وہ ہر وقت اس بات کا متوقع تھا کہ کسی روز اس کا بہترین دوست بھی اسے نہ پہچان سکے گا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ میں نے ضبط سے کام لیا۔ اور اپنے آنسوؤں کو رومال میں چھپا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
’’سلیم میں نے سُنا ہے کہ تم نے میرے لاہور جانے کے بعد یہاں بازاروں میں تقریریں کرنی شروع کر دی ہیں۔ جانتے بھی ہو۔ اب تمہیں شہر کا بچہ بچہ پاگل کے نام سے پُکارتا ہے۔ ‘‘
’’پاگل! شہر کا بچہ بچہ مجھے پاگل کے نام سے پُکارتا ہے۔ پاگل!۔ ہاں عباس، میں پاگل ہُوں۔ پاگل۔ دیوانہ۔ خرد باختہ۔ لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ یہاں تک کہ وہ میری طرف سرتاپا استفہام بن کر دیکھنے لگا۔ مگر میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ دوبارہ گویا ہوا۔
’’اس لیے کہ میں انہیں غریبوں کے ننگے بچے دِکھلا دِکھلا کر یہ پوچھتا ہُوں۔ کہ اس بڑھتی ہُوئی غربت کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟۔ وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے وہ مجھے پاگل تصّور کرتے ہیں۔ آہ اگر مجھے صرف یہ معلوم ہو کہ ظلمت کے اس زمانے میں روشنی کی ایک شعاع کیونکر فراہم کی جا سکتی ہے۔ ہزاروں غریب بچوں کا تاریک مستقبل کیونکر منّور بنایا جا سکتا ہے۔ وہ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ وہ جن کی نبضِ حیات دوسروں کے خون کی مرہون منّت ہے، وہ جن کا فردوس غربا کے جہنم کی مستعار اینٹوں سے استوار کیا گیا ہے، جن کے سازِ عشرت کے ہر تار کے ساتھ بیواؤں کی آہیں یتیموں کی عریانی، لاوارث بچوں کی صدائے گریہ لپٹی ہوئی ہے۔ کہیں، مگر ایک زمانہ آنے والا ہے جب یہی پروردہ ءِ غربت اپنے دلوں کے مشترکہ لہو میں اُنگلیاں ڈبو ڈبو کر ان لوگوں کی پیشانیوں پر اپنی لعنتیں لکھیں گے۔ وہ وقت نزدیک ہے جب ارضی جنّت کے دروازے ہر شخص کے لیے واہوں گے۔ میں پوچھتا ہُوں کہ اگر میں آرام میں ہوں۔ تو کیا وجہ ہے کہ تم تکلیف کی زندگی بسر کرو؟۔ کیا یہی انسانیّت ہے کہ میں کارخانے کا مالک ہوتے ہُوئے ہر شب ایک نئی رقاصہ کا ناچ دیکھتا ہُوں، ہر روز کلب میں سینکڑوں روپے قمار بازی کی نذر کر دیتا ہوں۔ اور اپنی نکمی سے نکمی خواہش پر بے دریغ روپیہ بہا کر اپنا دل خوش کرتا ہُوں، اور میرے مزدوروں کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے بچے مٹی کے ایک کھلونے کے لیے ترستے ہیں۔ پھر لُطف یہ ہے کہ میں مُہذب ہوں، میری ہر جگہ عزت کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جن کہ پسینہ میرے لیے گوہر تیار کرتا ہے۔ مجلسی دائرے میں حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ میں خود ان سے نفرت کرتا ہوں۔ تم ہی بتاؤ، کیا یہ دونوں ظالم و مظلوم اپنے فرائض سے نا آشنا نہیں ہیں؟ میں ان دونوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مگر کس طرح کروں؟۔ یہ مجھے معلوم نہیں۔ ‘‘
سلیم نے اس قدر کہہ کر ہانپتے ہوئے ٹھنڈی چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور میری طرف دیکھے بغیر پھر بولنا شروع کر دیا۔
’’میں پاگل نہیں ہُوں۔ مجھے ایک وکیل سمجھو۔ بغیر کسی اُمید کے، جو اس چیز کی وکالت کر رہا ہے۔ جو بالکل گم ہُو چکی ہے۔ میں ایک دبی ہوئی آواز ہوں۔ انسانیّت ایک منہ ہے۔ اور میں ایک چیخ۔ میں اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر وہ میرے خیالات کے بوجھ تلے دبی ہُوئی ہے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر اسی لیے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کہ مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ میں اپنا پیغام کہاں سے شروع کروں۔ یہ مجھے معلوم نہیں۔ میں اپنی آواز کے بکھرے ہوئے ٹکڑے فراہم کرتا ہوں ذہنی اذّیت کے دُھندلے غبار میں سے چند خیالات تمہید کے طور پر پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ اپنے احساسات کی عمیق گہرائیوں سے چند احساس سطح پر لاتا ہوں۔ کہ دوسرے اذہان پر منتقل کر سکوں مگر میری آواز کے ٹکڑے پھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ خیالات پھر تاریکی میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ احساسات پھر غوطہ لگا جاتے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں۔ کہ میرے خیالات منتشر ہونے کے بعد پھر جمع ہو رہے ہیں۔ تو جہاں کہیں میری قوتِ گویائی کام دیتی ہے میں شہر کے رؤسا سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگ جاتا ہوں۔ مرمریں محلّات کے مکینو! تم اس وسیع کائنات میں صرف سورج کی روشنی دیکھتے ہو۔ مگر یقین جانو۔ اس کے سائے بھی ہوتے ہیں۔ تم مجھے سلیم کے نام سے جانتے ہو، یہ غلطی ہے۔ میں وہ کپکپی ہوں جو ایک کنواری لڑکی کے جسم پر طاری ہوتی ہے۔ جب وہ غربت سے تنگ آکر پہلی دفعہ ایوانِ گناہ کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ آؤ ہم سب کانپیں! تم ہنستے ہو۔ مگر نہیں تمہیں مجھے ضرور سُننا ہو گا۔ میں ایک غوطہ خور ہُوں۔ قدرت نے مجھے تاریک سمندر کی گہرائیوں میں دبو دیا۔۔۔۔۔۔ کہ میں کچھ ڈھونڈھ کر لاؤں۔ میں ایک بے بہا موتی لایا ہُوں۔ وہ سچائی ہے۔ اس تلاش میں میں نے غربت دیکھی ہے، گرسنگی برداشت کی ہے۔ لوگوں کی نفرت سے دوچار ہُوا ہُوں۔ جاڑے میں غریبوں کی رگوں میں خون کو منجمد ہوتے دیکھا ہے، نوجوان لڑکیوں کو عشرت کدوں کی زینت بڑھاتے دیکھا ہے اس لیے کہ وہ مجبور تھیں۔ اب میں یہی کچھ تمہارے منہ پر قے کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں تصویر زندگی کا تاریک پہلو نظر آ جائے۔ انسانیت ایک دل ہے۔ ہر شخص کے پہلو میں ایک ہی قسم کا دل موجود ہے۔ اگر تمہارے بوٹ غریب مزدوروں کے ننگے سینوں پر ٹھوکریں لگاتے ہیں۔ اگر تم اپنے شہوانی جذبات کی بھڑکتی ہُوئی آگ کسی ہمسایہ نادار لڑکی کی عصمت دری سے ٹھنڈی کرتے ہو۔ اگر تمہاری غفلت سے ہزار ہا یتیم بچے گہوارہ ءِ جہالت میں پل کر جیلوں کو آباد کرتے ہیں۔ اگر تمہارا دل کاجل کے مانند سیاہ ہے۔ تو یہ تمہارا قصور نہیں۔ ایوان معاشرت ہی کچھ ایسے ڈھب پر استوار کیا گیا ہے۔ کہ اس کی ہر چھت اپنی ہمسایہ چھت کو دابے ہُوئے ہے۔ ہر اینٹ دوسری اینٹ کو۔ جانتے ہو، موجودہ نظام کے کیا معنی ہیں؟۔ یہ کہ لوگو ں کے سینوں کو جہالت کدہ بنائے۔ انسانی تلذد کی کشتی ہو اور ہوّس کی موجوں میں بہا دے، جوان لڑکیوں کی عصمت چھین کر انہیں ایوان تجارت میں کھلے بندوں حُسن فروشی پر مجبور کر دے غریبوں کا خون چُوس کر اُنہیں جلی ہوئی راکھ کے مانند قبر کی مٹی میں یکساں کردے۔ کیا اسی کو تم تہذیب کا نام دیتے ہو۔ بھیانک قصابی!! تاریک شیطنیت!!!ْ آہ اگر تم صرف وہ دیکھ سکو۔ جس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے!۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ جو قبر نما جھونپڑوں میں زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں۔ تمہاری نظروں کے سامنے ایسے افراد موجود ہیں۔ جو موت کے منہ میں جی رہے ہیں۔ ایسی لڑکیاں ہیں۔ جو بارہ سال کی عمر میں عصمت فروشی شروع کرتی ہیں۔ اور بیس سال کی عمر میں قبر کی سردی سے لپٹ جاتی ہیں۔ مگر تم۔ ہاں تم، جو اپنے لباس کی تراش کے متعلق گھنٹوں غور کرتے رہتے ہو۔ یہ نہیں دیکھتے۔ بلکہ اُلٹا غریبوں سے چھین کر اُمراء کی دولتوں میں اضافہ کرتے ہو۔ مزدور سے لے کر کاہل کے حوالے کر دیتے ہو۔ ڈگری پہنے انسان کا لباس اُتار کر حریر پوش کے سُپرد کر دیتے ہو۔ تم غربا کے غیر مختتم مصائب پر ہنستے ہو۔ مگر تمہیں یہ معلوم نہیں۔ کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاغر مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا۔ ‘‘
یہاں تک بول کر سلیم خاموش ہو گیا اور ٹھنڈی چائے کو آہستہ آہستہ پینے لگا۔ تقریر کے دوران میں میں سحر زدہ آدمی کی طرح چُپ چُپ بیٹھا اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو بارش کی طرح برس رہے تھے۔ بغور سنتا رہا۔ میں سخت حیران تھا۔ کہ وہ سلیم جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بالکل خاموش ہوا کرتا تھا۔ اتنی طویل تقریر کیونکر جاری رکھ سکا ہے۔ اس کے علاوہ خیالات کس قدر حق پر مبنی تھے۔ اور آواز میں کتنا اثر تھا۔ میں ابھی اس کی تقریر کے متعلق کچھ سوچ ہی رہا تھا۔ کہ وہ پھر بولا۔
’’خاندان کے خاندان شہر کے یہ نہنگ نگل جاتے ہیں۔ عوام کے اخلاق قوانین سے مسخ کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے زخم جُرمانوں سے کریدے جاتے ہیں۔ ٹیکسوں کے ذریعے دامنِ غربت کترا جاتا ہے۔ تباہ شدہ ذہنیت جہالت کی تاریکی سیاہ بنا دیتی ہے۔ ہر طرف حالت نزع کے سانس کی لرزاں آوازیں، عریانی، گناہ اور فریب ہے۔ مگر دعویٰ یہ ہے کہ عوام امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہماری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی جا رہی ہے۔ ہمارے کانوں میں پگھلا ہُوا سیسہ اُتارا جا رہا ہے۔ ہمارے جسم مصائب کے کوڑے سے بے حس بنائے جا رہے ہیں۔ تاکہ ہم نہ دیکھ سکیں۔ نہ سُن سکیں اور نہ محسوس کر سکیں!۔ انسان جسے بلندیوں پر پرواز کرنا تھا۔ کیا اس کے بال و پر نوچ کر اسے زمین پر رینگنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا رہا؟۔ کیا امرا کی نظر فریب عمارتیں مزدوروں کے گوشت پوست سے تیار نہیں کی جاتیں؟۔ کیا عوام کے مکتوبِ حیات پر جرائم کی مہر ثبت نہیں کی جاتی؟ کیا مجلسی بدن کی رگوں میں بدی کا خون موجزن نہیں ہے۔ کیا جمہور کی زندگی کشمکشِ پیہم، انتھک محنت اور قوتِ برداشت کا مرکب نہیں ہے؟۔ بتاؤ بتاؤ، بتاتے کیوں نہیں؟‘‘
’’درست ہے‘‘
میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔
’’تو پھر اس کا علاج کرنا تمہارا فرض ہے۔ کیا تم کوئی طریقہ نہیں بتا سکتے۔ کہ اس انسانی تذلیل کو کیونکر روکا جا سکتا ہے۔ مگر آہ! تمہیں معلوم نہیں، مجھے خود معلوم نہیں‘‘
تھوڑی دیر کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑ کر راز دارانہ لہجے میں یوں کہنے لگا۔
’’عباس! عوام سخت تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ بعض اوقات جب کبھی میں کسی سوختہ حال انسان کے سینے سے آہ بلند ہوتے دیکھتا ہوں۔ تو مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں شہر نہ جل جائے!۔ اچھا اب میں جاتا ہوں، تم لاہور واپس کب جا رہے ہو؟‘‘
’’یہ کہہ کر وہ اُٹھا۔ اور ٹوپی سنبھال کر باہر چلنے لگا۔
’’ٹھہرو! میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کہاں جاؤ گے اب؟‘‘
اسے یک لخت کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر میں نے اسے فوراً ہی کہا۔
’’مگر میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ کسی باغ میں جاؤں گا‘‘
میں خاموش ہو گیا۔ اور وہ ہوٹل سے نکل کر بازار کے ہجوم میں گم ہو گیا اس گفتگو کے چوتھے روز مجھے لاہور میں اطلاع ملی کہ سلیم نے میرے جانے کے بعد بازاروں میں دیوانہ وار شور برپا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس لئے اسے پاگل خانے میں داخل کر لیا گیا ہے۔
سعادت حسن منٹو
۲۴ مارچ ۱۹۳۵ء اشاعت اولیں، علی گڑھ میگزین