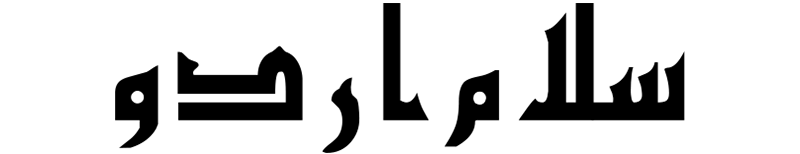کہانی کی کہانی
مفلسی میں پلے بڑھے ایک ایسے بچے کی کہانی، جو اسکول کے دنوں میں امی سے ملا تھا۔ اس کے بعد لاہور کے ایک بازار میں اس کی امی سے ملاقات ہوئی۔ تب وہ ایک دفتر میں نوکری کرنے لگا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ امی سے ملاقات کے بعد اسے اپنے دوست اور امی کے بیٹے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ انگلینڈ میں پڑھتا ہے۔ امی سے اس کی ملاقات بڑھتی جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ ہی رہنے لگتا ہے۔ ایک بار وہ انگلینڈ سے آئے اپنے دوست کا خط پڑھتا ہے جس میں ان سے دو ہزار روپیے کی مانگ کی گئی تھی۔ امی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ ان کے لیے اپنے زیور بیچنے جاتی ہے۔ وہ ان کے پیچھے ان کے بیگ سے پچاس روپیے چرا لیتا ہے اور جوا کھیلنے چلا جاتا ہے۔
وہ بڑے صاحب کے لیے عید کارڈ خرید رہاتھا کہ اتفاقاً اس کی ملاقات امی سے ہوگئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے امی سے آنکھ بچا کر کھسک جانا چاہا لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے اور وہ اپنی پتلون کی جیب میں اکنی کو مسلتارہ گیا۔ اچانک امی نے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ’’او سودی، تم کہاں؟‘‘ اس نے فوراً اپنی جیب سے ہاتھ نکال لیا اور ایک عید کارڈ اٹھا کر بولا، ’’یہیں، امی، میں تو یہیں ہوں۔‘‘
’’کب سے؟‘‘ امی نے حیرت سے پوچھا۔
’’تقسیم کے بعد سے امی میں بھی یہاں ہوں اور ماں اور دوسرے لوگ بھی۔‘‘
’’لیکن مجھے تمہارا پتہ کیوں نہ چلا۔ میں نے تمہیں کہیں بھی نہ دیکھا۔‘‘
اس کے جواب میں وہ ذرا مسکرایا اور پھر عید کارڈکا کنارہ اپنے کھلے ہوئے ہونٹوں پر مارنے لگا۔ دکان کے لڑکے نے بڑے ادب سے کارڈ اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے میز پر پھیلے ہوئے دوسرے کارڈوں میں ڈال کر اندر چلا گیا۔ امی نے اپنا پرس کھولتے ہوئے پوچھا، ’’اب تو تو اپنی ماں سے نہیں جھگڑتا؟‘‘
مسعود شرمندہ ہوگیا۔ اس نے عید کارڈوں پر نگاہیں جما کر کہا، ’’نہیں تو۔۔۔ میں پہلے بھی اس سے کب جھگڑتا تھا۔‘‘ امی نے کہا، ’’یوں تو مت کہہ۔ پہلے تو تو بات بات پر اس کی جان کھا جاتاتھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد برپا کردیتا تھا۔‘‘ اس نے صفائی کے طور پر امی کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر جواب دیا، ’’جب تو میں چھوٹا ساتھاامی۔ اب تووہ بات نہیں رہی نا۔‘‘ لیکن اس جواب سے امی کی تسلی نہ ہوئی اور اس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ ’’تیرا دوست تو یو۔کے چلا گیا، انجیئنرنگ کی تعلیم پانے۔ یہ عید کارڈ اسی کے لیے خرید رہی تھی۔‘‘
’’کہاں؟ انگلینڈ چلا گیا!‘‘ اس نے حیران ہو کر کہا، ’’جبھی تو وہ مجھ سے ملا نہیں۔ میں بھی سوچ رہا تھا اسے کیا ہوا۔ یہاں ہوتا اور مجھ سے نہ ملتا۔ کیسی حیرانی کی بات ہے۔‘‘ امی نے آہستہ سے دہرایا، ’’ہاں انگلینڈ چلا گیا۔ ابھی دو سال اور وہیں رہے گا۔ یہ عیدکارڈ اسی کے لیے خریدا ہے۔‘‘ اور اس نے کارڈ آگے بڑھا دیا۔ اس پر غریب الوطنی، دوری اور ہجرکے دو تین اشعار لکھے تھے۔ مسعود نے اسے ہاتھ میں لیے بغیر کہا، ’’لیکن یہ عید تک اسے کیسے مل سکے گا۔ عید تو بہت قریب ہے۔‘‘ امی نے وثوق سے کہا، ’’ملے گا کیسے نہیں۔ میں بائی ایئر میل جو بھیج رہی ہوں۔‘‘
’’لیکن بائی ائیر میل بھی یہ وقت پر نہ پہنچ سکے گا۔‘‘ مسعود نے جواب دیا۔ امی نے کہا، ’’تو کیا ہے۔ اسے مل تو جائے گا۔ ایک آدھ دن لیٹ سہی۔‘‘ اور مسعود کے کچھ کہنے سے پیشتر امی نے کہا، ’’کبھی ہمارے گھر تو آنا۔ تمہاری دیدی نے ایم۔ اے کا امتحان دے دیا ہے۔ ضرور آنا۔ عید پر چلے آنا۔ ہم اکٹھے عید منائیں گے۔‘‘ جب امی مسعود کو اپنا پتہ لکھا کر چلنے لگی تو اس نے اپنا فون نمبربتاتے ہوئے کہا، ’’آنے سے پہلے مجھے فون ضرور کرلینا۔ میں اکثر دورے پر رہتی ہوں، لیکن عید کے روز میں ضرور گھر پر ہوں گی۔ ‘‘ مسعود نے پتے کے ساتھ ایک کونے پر فون نمبر بھی لکھ لیا۔ امی نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ساڑھی کا پلو درست کرتے ہوئے دکان سے نیچے اتر گئی۔ مسعود نے پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اکنی کو چٹکی میں پکڑ لیا اور بڑے صاحب کے لیے عید کارڈ انتخاب کرنے لگا۔
مسعود کی ماں نے اپنے خاوند کی موت کے ایک سال بعد ہی اپنے کسی دور کے رشتہ دار سے شادی کر لی تھی۔ اول اول تو اس کی دوسری شادی کا مقصد مسعود کی تعلیم و تربیت تھی لیکن اپنے دوسرے خاوند کی جابرانہ طبیعت کے سامنے اسے مسعود کو تقریباً بھلا دینا پڑا۔ مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں جب مسعود کو اپنے چچا سے فیس مانگنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ کئی دن یونہی ٹال مٹول میں گزار دیتا۔ پیسوں کے معاملے میں اس کی ماں بالکل معذور تھی۔ گھر کے معمولی اخراجات تک کے لیے اسے اپنے خاوند کا منہ تکتے رہنا پڑا اور وہ اپنی کم مائیگی اور تہی دستی کا غصہ مسعود پر اتارا کرتی۔ ہر صبح اسے چولہے کے پاس بیٹھ کر چائے کی پیالی اور رات کی ایک باسی روٹی کے ساتھ یہ فقرہ ضرور سننا پڑا، ’’لے مرلے۔ تیری خاطر مجھے کیا کیا کچھ نہیں کرنا پڑا۔‘‘
یہ جملہ گو مسعود کو بہت ہی ناگوار گزرتا لیکن ہر روز ناشتے کے لیے یہ بل کچھ ایسا بڑا بھی نہ تھا اور فیس ادا کرنے کے دن تو اس بل میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا۔ اس کا چچا حقہ پیتے ہوئے کہتا، ’’پڑھتا وڑھتا تو ہے نہیں۔ یونہی آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ میں نے تیری ماں سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ تجھے ڈاکٹر بیگ کے یہاں بٹھا دیں تا کہ کچھ کمپاؤڈری کا کام ہی سیکھ لے۔ آگے چل کر تیرے کام آئے گا لیکن پتہ نہیں وہ کن خیالوں میں ہے۔‘‘ مسعود دونوں بانہیں سینے کے ساتھ لگا کر آہستہ سے جواب دیتا، ’’کام تو اچھا ہے جی، لیکن پہلے میں دسویں پاس کر لوں پھر۔۔۔‘‘ اور چچا صاحب طنز سے مسکرا کر ایک باچھ ٹیڑھی کر کے بیچ میں بول اٹھتے، ’’بس بس جیسی کو کو ویسے بچے! یہی بات تیری ماں کہا کرتی ہے۔ اسے جب معلوم ہوا گر خود کماکر تیری روز روز کی فیسوں کی چٹی بھرے، کتنی فیس ہے تیری؟‘‘
مسعود ذرا سہم کر جواب دیتا، ’’چار روپے تیرہ آنے جی!‘‘
’’اچھا اس مرتبہ تیرہ آنے کا اضافہ ہو گیا۔‘‘
’’کھیلوں کا چندہ ہے جی! ماسٹر جی نے کہا تھا کہ۔۔۔‘‘
’’تو کہہ دے اپنے ماسٹر واسٹر سے کہ میں کھیل نہیں کھیلتا اور تجھے شرم نہیں آتی کھیلیں کھیلتے ہوئے۔ اونٹ کی دم چومنے جتنا ہو گیا ہے اور کھیلیں کھیلتا ہے۔‘‘
مسعود آہستہ سے کھنکار کر جواب دیتا، ’’میں تو کچھ نہیں کھیلتا جی، پر ماسٹر جی کہتے ہیں کھیلو چاہے نہ کھیلو، لیکن چندہ ضرور دینا پڑے گا۔‘‘
’’یہ اچھا رواج ہے۔‘‘ اس کا چچا سر ہلا کر کہتا، ’’کھیلوچاہے نہ کھیلو، لیکن چندہ ضرور دو۔ سکول ہے کہ کمشنر کا دفتر۔ چندہ نہ ہوا، وار فنڈ ہوا۔‘‘
چونکہ عام طور پر ایسی بات کا جواب مسعود کے پاس نہ ہوتا، اس لیے وہ خاموش ہی رہتا۔ اس کے بعد چچا پاس ہی کھونٹی پر لٹکتی ہوئی اچکن سے پانچ روپے کا نوٹ نکال کر کہتا، ’’لے پکڑ۔ اپنی ماں کو بتادینا اور سکول سے لوٹتے ہوئے باقی کے تین آنے مجھے دفتر دے جانا۔‘‘
خوف، نفرت اور تشکر کے ملے جلے جذبات سے مسعود کی آنکھیں پھٹتیں، بند ہوتیں اور پھر اپنی اصلی حالت پر آجاتیں اور وہ نوٹ اپنی مٹھی میں دبا کر ماں کو بتانے دوسرے کمرے کی طرف چل پڑتا اور اس کا چچا اپنے کمرے میں حقہ بجاتے ہوئے ہانک لگاتا، ’’فیس دے دی ہے جی تمہارے شہزادے کو۔ ڈپٹی صاحب کو !‘‘ یہ سنتے ہی مسعود ایک دم رک جاتا اور جی ہی جی میں اپنی ماں کو ایک گندی سی گالی دے کر وہ الٹے پاؤں اپنی کوٹھری میں جا کر بستہ باندھنے لگتا۔ چچا جیسے بیہودہ آدمی سے شادی کر کے اس کی ماں اس کی نگاہوں میں بالکل گر چکی تھی اور وہ چچا کی طعن آمیز باتوں کا بدلہ ہمیشہ اپنی ماں کو گالی دے کر چکایا کرتا۔
تفریح کی گھنٹی میں درختوں کے سائے تلے اپنے کھیلتے ہوئے ہم جولیوں کی دعوت سے انکار کر کے اسے سیدھا گھر بھاگنا پڑتا۔ خاصہ دان تیار ہوتا جسے اٹھا کر وہ جلدی جلدی اپنے چچا کے دفتر پہنچتا اور اسے ان کی کرسی کے پاس رکھ کر بغیر کچھ کہے سکول بھاگ آتا۔ عرصہ سے اس کی تفریحی گھنٹیاں یونہی ضائع ہو رہی تھیں۔ صرف اتوار کے دن اسے اپنے چچا کے دفتر نہ جانا پڑتا، لیکن اتوار کو کوئی تفریح کی گھنٹی نہیں ہوتی۔
آٹھویں جماعت کے سالانہ امتحان سے پہلے اس کے یہاں ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوا جس کا نام اس کی ماں کے اصرار کے باوجود مقصود کی بجائے نصراللہ رکھا گیا۔ اس بھائی کی پیدائش نے مسعود سے اس کی ماں کو قطعی طور پر چھین لیا اور اس کی حیثیت گھر میں کام کرنے والے نوکر سی ہو کر رہ گئی، جو اپنا اصلی کام ختم کرنے کے بعد پڑوس کے دروازے کی اونچی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بچے کھلایا کرتا ہے۔ نصراللہ کی آمد کے دن سے مسعود کا چچا دن میں بارہا ڈاکٹر بیگ کا وظیفہ کرنے لگا اور مسعود کی ماں سے تقاضا کرتا رہا کہ چونکہ اب نصراللہ ہو گیا ہے، اس کے اخراجات بھی ہوں گے، اس لیے مسعود کو سکول سے اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے یہاں بٹھا دینا چاہیے لیکن اس کی ماں نہ مانی اور سلسلہ یونہی چلتا رہا۔
یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسعود کے سکول میں موسم کے طلسماتی کارڈ بیچنے ایک آدمی آیا اور اس کی وجہ سے مسعود کی ملاقات امی سے ہوئی۔ گلریز اپنی بیوہ امی کا ایک ہی لڑکا تھا اور مسعود کا ہم جماعت تھا۔ جماعت بھر میں مسعود کی دوستی صرف گلریز سے تھی۔ دونوں کو ننھی ننھی ٹوکریاں بنانے کا خبط تھا۔ پڑھائی کے دوران میں اگر کبھی انہیں فرصت کے چند لمحات میسر آجاتے تو وہ سائنس روم کے دروازوں سے چمٹی ہوئی عشق پیچاں کی بیلوں سے ادھ سوکھی لمبی لمبی رگیں توڑتے اور کھیل کے میدان میں ہری ہری گھاس پر ٹوکریاں بنانے لگتے، جس میں گلاب کا ایک پھول یا چنبیلی کی چند کلیاں مشکل سے سما سکتیں۔ مسعود دستی والی ٹوکری بھی بنا لیتا تھا لیکن گلریز سے ہزار کوششوں کے باوجود بھی ایسی ٹوکری نہ بن سکتی تھی اور وہ مسعود کی بنائی ہوئی ٹوکری لے لیا کرتا۔
ہاں توجس دن ان کے سکول میں موسم کے طلسماتی کارڈ بیچنے والا آدمی آیا، مسعود کی ملاقات امی سے ہوئی۔ سفید کارڈوں کے بیچوں بیچ گلابی رنگ کا ایک بڑا سا سرخ دائرہ تھا، جس پر ایک خاص مصالحہ لگا ہوا تھا۔ کارڈ بیچنے والے نے بتایا کہ جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا رہے گا، اس دائرے کے رنگ بھی بدلتے رہیں گے۔ جوں جوں گرمی بڑھتی جائے گی، گلابی دائرہ سرخ ہوتا جائے گا اور جب سردی کا زور ہوگا تو یہ گلابی چکر بسنتی رنگ کا ہو جائے گا اور جس دن مطلع ابر آلود ہوگا اور بارش برسنے کا امکان ہوگا تو یہ چکر خودبخود دھانی رنگ کا ہو جائے گا۔ کارڈ کی قیمت دو آنے تھی۔ کلاس میں تقریباً سب نے وہ کارڈ خریدے اور جن کے پاس دو آنے نہ تھے، انہوں نے بات اگلے دن پر اٹھا دی۔
گھر سے خاصہ دان اٹھاتے ہوئے مسعود نے ہولے سے کہا، ’’اماں، مجھے دو آنے تو دو میں۔۔۔‘‘ مگر اس نے تیزی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، ’’میرے پاس کہاں ہیں دو آنے۔ کبھی مجھے پیسے چھوتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ کون لالا کے میری جھولیاں بھرتا ہے جو تجھے دونی دوں۔‘‘
مسعود نے مایوس ہو کر خاصہ دان اٹھا لیا اور چپ چاپ دروازے سے باہر نکل گیا۔۔۔ دفتر پہنچ کر اس نے خاصہ دان کرسی کے پاس رکھ دیا اور خلاف معمول وہاں کھڑا ہوگیا۔ اس کے چچا نے فائل میں کاغذ پروتے ہوئے عینک کے اوپر سے دیکھا اور ترش رو ہو کر پوچھا، ’’کیوں؟ کھڑا کیوں ہے؟‘‘
’’کچھ نہیں جی۔‘‘ مسعود کا گلا خشک ہو گیا۔
’’کچھ تو ہے۔‘‘
’’نہیں جی کچھ بھی نہیں۔‘‘ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔
’’تو پھر فوجیں کیوں کھڑی ہیں؟‘‘
’’جی ایک دونی چاہیے۔۔۔ اماں۔۔۔ میں۔۔۔ سکول میں جی۔۔۔ ماں۔۔۔‘‘
’’بلوں ماں‘‘ اس کے چچا نے غرا کر کہا، ’’تجھے دونی دوں! تجھے ناواں دوں! میرے بورے جو ڈھوتا رہا ہے۔ میرے ساتھ جو کھیلتا رہا ہے۔‘‘
مسعود شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، ’’میں میں۔۔۔ اماں نے۔۔۔ اماں نے۔۔۔ جی سکول۔۔۔ سکول میں۔۔۔‘‘
’’ہوں۔‘‘ اس کے چچا نے گرج کر کہا ’’تجھے پیسے دوں! تجھے دونیاں دوں۔ کیوں؟ مجھے بین سناتا رہا ہے۔ مجھے نبض دکھاتا رہا ہے۔ تجھے پیسے دوں۔ ہوں تجھے دونی دوں۔۔۔ تجھے۔۔۔‘‘
مسعود نے ایک نگاہ خاصہ دان کو غور سے دیکھا جو واقعی ان کی باتیں نہیں سن رہا تھا اور پھر اپنے چچا کو اسی طرح ہوں ہوں کرتے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھپریل کے برآمدے میں بنچ پر بیٹھا ہوا ایک بوڑھا چپراسی آپ ہی آپ کہے جارہا تھا، ’’ہوں! تجھے پیسے دوں! تجھے ناواں دوں۔ میرے بورے جو ڈھوتا ہے۔ ہوں تجھے پیسے دوں۔‘‘
اور راستہ بھر مسعود کو ایسی ہی آوازیں آتی رہیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا اس کے ٹخنوں کے درمیان چھوٹا سا گراموفون لگاہوا ہوا ور جس کا ریکارڈ اس کی رفتار کے مطابق گھومتا ہو۔ مسعود نے سڑک کے کنارے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا اور ریکارڈ اونچے اونچے بجنے لگا، ’’تجھے پیسے دوں، تجھے پیسے دوں، میرے بورے جو میرے بورے جو۔‘‘ مسعود نے گھبرا کر راہ چلتے لوگوں کو غور سے دیکھا کہ وہ بھی تو یہ ریکارڈ نہیں سن رہے اور پھر اپنی رفتار بالکل سست کر دی۔ گراموفون کی چابی ختم ہوگئی اور ریکارڈ سسکنے لگا، ’’تجھے پیسے۔۔۔ دوں۔۔۔ تجھے ناواں۔۔۔ دوں۔۔۔ میرے۔۔۔ بورے۔۔۔ جو۔۔۔‘‘ اور سکول تک یہ باجا یونہی بجتا رہا۔
سکول بند ہونے پر گلریز نے خود ہی اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی کہ طلسماتی کارڈ اپنے کمرے میں لٹکا کر اور سارے دروازے بند کر کے دیکھیں گے کہ گرمی سے دائرہ سرخ ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ تجسس مسعود کو کشاں کشاں ان کے گھر لے گیا۔ گول گول غلام گردش والے برآمدے کے ایک کونے میں سفید رنگ کی ساڑھی باندھے ادھیڑ عمر کی ایک دبلی سی عورت جالی کے دروازے کو دھاگے سے ٹانکے لگا رہی تھی۔ اس کا سر ننگا تھا اور کندھوں پر سلیٹی رنگ کی بنی ہوئی ایک اونی شال پڑی تھی۔ مسعود نے ایک نظر اس کے ننھے سے وجود کو دیکھا جس سے سارا برآمدہ بھرابھرا معلوم ہوتا اور سیڑھیوں پر ٹھٹک گیا۔ اسے اس طرح دم بخود دیکھ کر گلریز نے بے تکلفی سے بستہ چارپائی پر پھینک کر کہا، ’’آؤ۔ آؤ۔‘‘
اور پھر سیمنٹ کے فرش پر تیزی سے اپنے بوٹ گھسیٹتا وہ اس عورت کے پاس جا کھڑا ہوا ا ور چلانے لگا، ’’امی امی! میں نے ایک چیز خریدی۔ ایک نئی چیز، جادو کا کارڈ۔۔۔ دیکھو امی۔‘‘ اور اس کی امی نے گردن موڑ کر اور کارڈ ہاتھ میں لے کر کہا، ’’اچھا ہے۔ بڑا اچھا۔‘‘ اور پھر اس کی نگاہیں برآمدے میں رینگتے ہوئے اس لڑکے پر پڑیں، جس نے ٹخنوں سے اونچی میلی شلوار پہن رکھی تھی اور جس کی خاکی کینوس کے جوتوں سے اس کی انگلیاں باہر جھانک رہی تھیں۔ گلریز نے شرماتے ہوئے کہا، ’’یہ میرا دوست مسعود ہے۔ امی یہ میرے ساتھ پڑھتا ہے۔ یہ میرے ساتھ اس کارڈ کو رنگ بدلتے ہوئے دیکھنے آیا ہے۔‘‘ امی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے غور سے مسعود کو دیکھا۔ خوش آمدید کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی اور وہ بڑے پیار سے بولی، ’’تم نے کارڈ نہیں خریدا مسعود؟‘‘
اور مسعود کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کی برسوں کی واقف ہو۔ مسعود اس کے صحن میں کھیل کر اتنا بڑا ہواہو اور وہ مسعود کو لمبی لمبی کہانیاں سنا کر ہر رات کہا کرتی رہی ہو، ’’اب تم سو جاؤ۔‘‘
گلریز نے اپنے کارڈ کے دائرے پر فخر سے انگلی پھیرتے ہوئے کہا، ’’اس نے نہیں خریدا امی۔ اس کے پاس دونی نہیں تھی۔ اس کے پاس کبھی بھی پیسے نہیں ہوئے۔‘‘ امی نے کہا، ’’تو اچھا دوست ہے۔ اس نے نہیں خریدا تو تو نے دو کارڈ کیوں نہ خرید لیے؟ تیرے پاس تو پیسے تھے۔‘‘ گلریز نے گھبرا کر جواب دیا، ’’باقی پیسوں کی تو میں نے برفی کھالی تھی اور ایک آنے کی پنسل خریدی تھی۔‘‘ امی نے کہا، ’’تو تجھے اپنے دوست سے برفی پیاری ہے۔‘‘
’’نہیں جی۔ امی۔‘‘ گلریز شرمندہ ہو گیا اور اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ کے کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں سرخ رنگ کے صوفے پر ایک لڑکی سویٹر بن رہی تھی۔ اس کے پہلو میں چینی کی ایک چھوٹی سی رکابی میں کھلیں پڑی تھیں۔ گلریز نے اندر داخل ہو کر کہا، ’’دیکھو، دیدی، دیکھو، میرے پاس جادو کا کارڈ ہے۔‘‘
اور دیدی نے سلائیوں سے نگاہیں اٹھائے بغیر کہا، ’’اچھا ہے۔‘‘ مسعود دیدی کا رویہ دیکھ کر باادب ہو گیا اور گلریز خفیف ہو کر جالی کا دروازہ زور سے چھوڑکر باہر نکل گیا۔ دیدی نے ماتھا سکیڑ کر کہا، ’’آہستہ‘‘ اور پھر سوالیہ نگاہوں سے مسعود کو دیکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ مسعود نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہولے سے آگے بڑھا۔ دھیرے سے جالی کا دروازہ کھولا اور اسے بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ بند کرتے ہوئے گلریز کے پیچھے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر گلریز نے کارڈ میز پہ ڈال کر کہا، ’’دروازہ بند کرو یار۔ کمرہ گرم ہو جائے گا تو کارڈ رنگ بدلے گا۔‘‘ دروازہ بند ہوگیا۔ وہ دیر تک کارڈ پر نگاہیں جمائے بیٹھے رہے مگر اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا۔ مسعود نے کہا، ’’گلریز میاں، گرمی کم ہے اس لیے رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ باورچی خانے میں چولہے کے پاس کارڈ رکھیں گے تو یہ ضرور سرخ ہو جائے گا۔‘‘
جب باورچی خانے میں پہنچے تو امی گوبھی کاٹ رہی تھیں۔ گلریز نے ایک چوکی چولہے کے پاس کھنچ کر اس پر کارڈ ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ ٹماٹر کی طرح سرخ ہوگیا۔
امی سے یہ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ جب وہ اسے پھلوں اور بسکٹوں والی چائے پلاکر گھر کے دروازے تک چھوڑنے آئیں تو باورچی خانے سے چرائی ہوئی چونی مسعود کی جیب میں انگارے کی طرح دہکنے لگی اور وہ جلدی سے سلام کر کے ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے امی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا او وہ سارا دن ان کے گھر ہی رہنے لگا۔
تقسیم کے بعد جہاں سب لوگ تتر بتر ہوگیے، وہاں امی اور مسعود بھی بچھڑ گیے اور پورے تین سال بعد آج ان کی ملاقات عیدکارڈوں کی دکان پر ہوئی تھی۔ مسعود نے اپنی کوٹھری تو نہیں چھوڑی تھی لیکن وہ دفتر کے بعد کا تقریباً سارا وقت امی کے یہاں گزارنے لگا۔ دیدی نے واقعی ایم۔ اے کا امتحان دے دیا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ متکبر ہوگئی تھی۔ بریکٹ پر ایک بڑے سے پھول دان میں وہ سرکنڈوں کے پھول لگائے موٹی موٹی کتابیں پڑھا کرتی۔ اس کی آواز جو پہلے نرگس کے ڈنٹھل کی طرح ملائم تھی، خشک او ر کھردری ہو گئی تھی۔ یوں تو وہ دن بھر میں مشکل سے ہی چند جملے بولتی لیکن جب بات کرتی تو یوں لگتا گویا خشک اسفنج کے ٹکڑے اگل رہی ہو۔ امی جب بھی اس سے بات کرتی، بڑے ادب اور رکھ رکھاؤ سے کا م لے کر۔ واقعی دیدی نے ایم۔ اے کا امتحان دے دیا تھا۔
امی نے کئی مرتبہ مسعود سے اس کی ماں اور چچا کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ ’’یہیں کہیں رہتے ہیں۔ مجھے علم نہیں۔‘‘
دفتر سے فارغ ہو کر مسعودسیدھا امی کے یہاں پہنچتا اور رات کو دیر تک ادھر ادھر کی بے معنی گپیں ہانکتا رہتا۔ دیدی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی۔ وہ دو تین مرتبہ تیز تیز نگاہوں سے امی اور مسعود کو گھورتی اور پھر ٹھپ سے کتاب بند کر کے اندر کمرے میں چلی جاتی۔ جب دیدی مسعود کی پہنچ سے باہر ہو جاتی تو وہ زور زور سے قہقہے لگا کر اس کی پڑھائی میں مخل ہونے لگتا۔ امی کو پتہ تھا کہ وہ جان بوجھ کر دیدی کو تنگ کررہا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی مسعود کو منع نہیں کیا۔ ایک رات جب اسے باتیں کرتے کرتے کافی دیر ہوگئی تو امی نے کہا، ’’اب یہیں سو رہو۔ اس وقت اتنی دور کہاں جاؤ گے۔‘‘ تو مسعود وہیں سو رہا اور اس رات کے بعد وہ مستقل طور پر اسی کے یہاں رہنے لگا۔
چچا کی بخیل فطرت اور ماں کی لاپروائی اس کی آزادانہ زندگی پر ایک عجیب طرح سے اثر انداز ہوئی۔ وہ پہلے جس قدر گم صم رہتا تھا، اب اسی قدر ہنسوڑ ہو گیا تھا اور اپنے بچپن کی غریبی کا مداوا کرنے کے لیے اس نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتے ہی وہ تنگ و تاریک کوچوں میں سے گذرتا ہوا اس اندھی گلی میں پہنچ جاتا جس کے آخر میں پرانے چھپر اور پھونس کے ڈھیر پڑے ہوتے۔ پھونس کو ایک طرف ہٹا کر مسعود اندھیرے بھٹ میں داخل ہوتا جس کے پیچھے کچی اینٹوں کی ایک غلیظ سی کوٹھری، کڑوے تیل کا دیا اپنی آغوش میں لیے اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چیتو، بھمبیری اور ڈھلن نشہ پانی کیے فرش پر لیٹے ہوتے اور ریباں چھوٹے سے دروازے کے ٹوٹے ہوئے پٹ سے پشت لگائے ہولے سے کہتی، ’’آگیا، راجہ نل آگیا۔‘‘ اور پریل شروع ہو جاتی۔ مسعود کا ذہن اور مقدر مل جل کر ایسے ایسے معرکے مارتے کہ ہارنے کی نوبت کم آتی اور جب تک مسعود کی جیبیں خالی نہ ہوجاتیں اسے کل نہ پڑتی۔ وہ تاش پھینٹے جاتا، نقدی کی ڈھیریاں لگائے جاتا اور پریل کھیلے جاتا حتیٰ کہ اس کے مخالفوں کے پاس ایک چھدام بھی نہ رہتا یا اس کی جیبوں کا استر مردہ گائے کی زبان کی طرح باہر لٹکنے لگتا۔
امی کو پتہ تھا کہ مسعود نوکر ہو کر بڑا ہی زندہ دل اور چست ہو گیا ہے لیکن اس بات کا اسے علم نہ تھا کہ پریل کھیلتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی قینچی کی طرح چلنے لگتی ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو امی اس کا بستر بچھا کر آدھی رات تک اس کا انتظار کرتے ہوئے سوچا کرتی کہ گلریز بھی یونہی آوارہ گردی کرتاہوگا اور اس کی لینڈ لیڈی اس کا انتظار اسی طرح کیا کرتی ہوگی۔ پھر مسعود اور گلریز آپس میں گڈمڈ ہو جاتے۔ امی اور لینڈ لیڈی ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتیں اور شفقت لاابالی کا انتظار کرنے لگتی۔ دیدی اپنے بستر پر ایک دو مصنوعی کروٹیں بدل کر آتش بار نگاہوں سے امی کو گھورتی اور پھر منہ دوسری طرف کرکے دم سادھ لیتی۔ مسعود جب پھاٹک کے قریب پہنچتا تو پنجوں کے بل چلنے لگتا۔ شور مچانے والے پٹ کو آہستہ سے دھکیلتا اور پھر اندر داخل ہو کر اسے اسی طرح بند کر نے لگتا کہ امی پکار کر پوچھتی،
’’کہاں سے آئے ہو؟‘‘
’’کہیں سے نہیں امی۔‘‘ وہ سہم جاتا۔
’’نہر پر دوستوں کے ساتھ گپیں مار رہا تھا۔‘‘
’’یہ تمہارے کون سے ایسے دوست ہیں ذرا میں بھی تو دیکھوں۔‘‘
’’میرے دفتر کے ساتھی ہیں امی۔ دفتر کی باتیں ہو رہی تھیں۔‘‘ اور وہ آرام سے آکر اپنے بستر پر بیٹھ جاتا اور اپنے بوٹ کھولنے لگتا۔ امی خاموشی سے اٹھ کر اندر آجاتی اور کٹ کیٹ کا پیکٹ اس کے بستر پر پھینک کر بے پروائی سے کہتی، ’’میں آج بازار گئی تھی اور تیرے لیے یہ لائی تھی۔ آدھی اپنی دیدی کے لیے رکھ لینا۔‘‘ اور جب وہ بستر پر لیٹنے لگتا تو امی کہتی، ’’یہ تو اپنے بالوں پر اتنا تیل کیوں تھوپ لیتا ہے۔ لے کے سارے تکیے تیلی کی صدری بنا دیے ہیں۔ صبح ہونے دے تیرے سر پر استرا پھرواتی ہوں۔‘‘ اور مسعود کوئی جواب دیے بغیر سفید چادر اوڑھ کر مردے کی طرح سیدھا شہتیر لیٹ جاتا تو امی جل کر کہتی، ’’تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے یوں نہ لیٹا کر۔ یا تو کروٹ بدل یا ٹانگوں میں خم ڈال۔ اس طرح لیٹنے سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔‘‘ مسعود کروٹ بدل کر سوجاتا اور لینڈ لیڈی اطمینان کی سانس لے کر لباس تبدیل کرنے چلی جاتی۔
امی گلریز کا ہر خط مسعود کو ضرور دکھاتی اور پھر اتنی مرتبہ اس سے پڑھوا کر سنتی کہ مسعود کو الجھن ہونے لگتی اور وہ خط پھینک کر باہر چلا جاتا۔ گلریز کے ہر خط میں یا تو روپوں کا مطالبہ ہوتا یا گرم کپڑوں اور دیگر معمولی معمولی چیزوں کا جن کا بندوبست امی بڑے انہماک سے کیا کرتی۔ پارسل سیے جاتے۔ ان پر لاکھ کی مہریں لگتیں اور پھر مسعود کو انہیں ڈاک خانے لے جانا پڑتا۔
تنخواہ ملنے میں ابھی کئی دن پڑے تھے۔ بھمبیری مسعود کو سڑک پر مل گیا۔ اس نے بتایا کہ ان کی چوکڑی میں ایک بڑا مال دار کباڑیا رکنا داخل ہو گیا ہے جو صرف ہزاروںکی بازی لگاتا ہے۔ مسعود کے استفسار پر بھمبیری نے بتایا کہ وہ ہر روز اپنے ایک گماشتے لالوکا نے کے ساتھ گپھا میں آتا ہے اور نشہ پانی کر کے چلا جاتا ہے۔ مسعود نے ڈاک خانے کے پچھواڑے جا کر گرم سوٹ کا پارسل کھولا اور ماسٹر غلام حسین کی دکان پر جا کر ڈیڑھ سو روپے میں بیچ دیا۔ اس رات وہ گھر نہیں گیا۔ اس کا بستر تمام رات ٹھنڈا رہا اور اس کی پائنتی پر پڑی سفید چادر امی کی طرح ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی۔ صبح جب وہ گھر پہنچا تو نہ اس کے پاس روپے تھے اور نہ پارسل کی رسید۔ امی نے رات بھر غائب رہنے کے واقعہ کی طرف اشارہ کیےبغیر اس پوچھا، ’’پارسل کروا دیا تھا؟‘‘
’’کروا دیا تھا۔‘‘ اس نے رکھائی سے جواب دیا۔
’’اور رسید؟‘‘ دیدی نے پوچھا۔
مسعود نے گھور کر دیدی کو دیکھا اور کہا، ’’رات میں جس دوست کے یہاں سویا تھا رسید وہیں رہ گئی۔‘‘
امی نے چائے کی پیالی بناتے ہوئے پوچھا، ’’چھ روپے میں کام بن گیا تھا۔‘‘
’’نہیں۔‘‘ مسعود نے آہستہ سے کہا، ’’ساڑھے سات روپے کے ٹکٹ لگے۔ میں نے ڈیڑ ھ روپیہ ادھار لے لیا تھا۔‘‘ اور ڈیڑھ کا لفظ آتے ہی چائے اس کے حلق میں پھنس گئی۔ مسعود کو معلوم تھا امی کی تنخواہ تین چار سو کے لگ بھگ ہے۔ اس نے جی ہی جی میں اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ ایک پارسل کے نہ پہنچنے سے وہ مر نہیں جائے گی۔ ایک دن جب دیدی کے ڈریسنگ ٹیبل سے پچیس روپے گم ہو گیے تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے بلا سوچے سمجھے امی سے کہہ دیا کہ یہ کارستانی مسعودکی ہے۔ امی بجائے خفا ہونے کے رو کر کہنے لگی، ’’آج تو مسعود پر الزام دھرتی ہے کل مجھے چور بتائے گی۔۔۔ وہ بھلا تیرے پیسوں کا بھوکا ہے؟‘‘ لیکن دیدی نہ مانی اور ماں بیٹی میں خوب خوب تکرار ہوئی۔ شام کو نہ امی نے کھانا کھایا اور نہ دیدی نے، لیکن اس رات مسعود کا پانسہ بھاری رہا اور اس نے اپنے ساتھ بھمبیری اور چیتو کو بھی نان کباب کھلائے۔
گلریز کا خط آگیا تھا کہ اسے پارسل نہیں ملا۔ ڈاک خانے میں پوچھ گچھ ہوئی۔ رسید کی ڈھنڈیا پڑی لیکن نہ رسید ملی نہ پارسل کا پتہ چلا اور امی ڈاک خانے کو رو پیٹ کر خاموش ہو رہی، لیکن اس مرتبہ نہ تواس نے گلریز کا خط مسعود کو دکھایا اور نہ ہی اس سے پڑھوا کر سنا۔ اس نئے رویے نے مسعود کو یونہی تجسس میں ڈال دیا۔ اس نے ایک دو مرتبہ امی سے خط کے بارے میں پوچھا بھی لیکن وہ یہی کہہ کرخاموش ہو گئی کہ ’’میں کہیں ڈال کر بھول گئی ہوں۔‘‘ خط گھر ہی میں تو تھا، جاتا کہاں، مسعود کی تفتیش نے اسے امی کی میز سے ڈھونڈ نکالا۔ گلریز نے لکھا تھا، ’’پارسل مجھے نہیں ملا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہاں سردی بڑھتی جارہی ہے اور میں سخت پریشان ہوں لیکن سب سے بڑی پریشانی روپے کی ہے۔ مجھے نئی کلاس میں داخلہ لینا ہے جس کے لیے مجھے کم از کم دوہزار روپوں کی ضرور ت ہوگی، لیکن امی تم یہ دوہزار روپیہ کہاں سے لاؤ گی۔ مجھے علم ہے کہ تمہارے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ پر میں کروں بھی تو کیا! تعلیم ادھوری چھوڑ کر ایک ہی ڈگری لے کر آجاؤں۔۔۔‘‘
اس کے آگے مسعود نے کچھ نہ پڑھا۔ خط تہہ کیا اور دراز میں رکھ کر دفتر چلا آیا۔ اسے امی کی تنخواہ کے بارے میں علم تھا اور اس کے اندوختہ کے متعلق بھی اندازہ تھا لیکن گلریز کے اس خط نے اس کے سارے اندازوں پر پانی پھیر دیا۔ سارا دن وہ بے شمار ننھے ننھے سوالوں میں گھرا ٹائپ کرتارہا اور آخر اسی نتیجہ پر پہنچا کہ امی نے گلریز کو بھی دھوکے میں رکھ چھوڑا ہے تا کہ وہ غیر ملک میں عیاشیوں پر نہ اتر آئے۔ شام کو وہ معمول سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ پھاٹک پر ٹانگہ کھڑا تھا۔ دیدی کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور امی اندر اپنے کمرے میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ مسعود دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ امی اپنے بڑے سیاہ ٹرنک سے زیور نکال نکال کر انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی اور پھر اپنے پرس میں ڈالے جاتی۔ ٹرنک بند کرکے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے سنہری انگوٹھی اتار کر بھی اسی پرس میں ڈال لی۔ جب وہ اٹھ کر چلنے لگی تو مسعود نے اندر داخل ہو کر کہا، ’’کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟‘‘
امی گھبرا گئی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے کام لیتے ہوئے کہا، ’’اچھاہی ہوا تم آگیے۔ میں بازار جارہی تھی۔ تھوڑا سا کپڑا خریدنا ہے۔ تم گھر پر ہی رہنا تمہارے لیے کٹ کیٹ لاؤں گی۔‘‘ مسعود نے کہا، ’’امی ہمیں تو آج اس لیے جلدی چھٹی ہوگئی ہے کہ ہمارے دفتر کی ٹیم ریلوے کلب سے فٹ بال کھیل رہی ہے اور میں چھاؤنی جارہا ہوں۔ میں گھر پر رہ کر کیا کروں گا۔دینو جو یہاں موجود ہے۔‘‘ امی نے کہا، ’’اسے میں ساتھ لیے جارہی تھی لیکن خیر اب وہی گھر پر رہے گا۔۔۔ تم چائے پی لینا۔ تمہارے لیے انڈے ابال کر میں نے تھرموس میں رکھ دیے ہیں۔‘‘
امی چلی گئی۔ مسعود نے اپنا کوٹ اتار کر کھونٹی پر لٹکا دیا اور خود کرسی پر دراز ہو کر اخبار دیکھنے لگا۔ دینو چائے تپائی پر رکھ کر تمباکو لینے چلا گیا۔ مسعود نے اسی طرح اخبار گود میں ڈالے ایک پیالی پی۔ تھرموس کھول کر ایک انڈا نکالا اور بغیر نمک لگائے کھا گیا۔ دینو کو بازار گیے کافی دیر ہو چکی تھی اور اس کے لوٹ آنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ مسعود اٹھا۔ دیدی کے ٹرنک سے کروشیا نکالا اور امی کے کمرے میں جا کر اٹیچی کیس کھولنے لگا۔ اوپر ہی قرمزی رنگ کی ایک ریشمی ساڑھی کی تہہ میں پچاس روپے پڑے تھے۔ روپے اٹھا کر اس نے جیب میں رکھ لیے اور پھر تالا بند کرنے لگا، لیکن زنگ آلود پھاٹک کے کھلنے پر وہ چونک پڑا اور گھبراہٹ میں کروشیا بھی جیب میں ڈال کر باہر آگیا۔ مسعود نے دینو کو گھورتے ہوئے پوچھا ’’اتنی دیر کر دی تھی۔ کہاں چلا گیا تھا؟‘‘
’’جانا کہاں تھا؟‘‘ دینو نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، ’’بنا بنایا تمباکو دکاندار کے پاس تھانہیں، میں اگلی دکان پر گڑ لینے چلا گیا۔‘‘
’’اچھا‘‘ مسعود نے بے پروائی سے کہا، ’’امی سے کہہ دینا میں ذرا دیر سےآؤں گا اور کھانا نہیں کھاؤں گا۔‘‘
سپرنٹنڈنٹ کے یہاں پہنچ کر مسعود نے اپنے چہرے پر مسکینی کے ایسے آثار پیدا کیے کہ وہ پسیج گیا اور اس نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر ڈیڑھ سو روپیہ لا کر مسعود کو دے دیا اور لجاجت آمیز لہجے میں کہنے لگا، ’’مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ دو سو روپے اس وقت میرے پاس نہیں۔ شاید یہ رقم تمہاری والدہ کو موت کے منہ سے بچا سکے۔‘‘ اور جب مسعود اٹھ کر جانے لگا تو سپرنٹنڈنٹ نے کہا، ’’جنرل وارڈ کے انچارج ڈاکٹر قدیر میرے واقف ہیں۔ کہو تو انہیں ایک رقعہ لکھ دوں۔‘‘ مسعود نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، ’’اگر ایسا کر دیجئے تو میری دنیا بن جائے۔ خواجہ صاحب میرا اس جہاں میں سوائے میری ماں کے اور کوئی نہیں۔‘‘
سپرنٹنڈنٹ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ’’گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہاری والدہ راضی ہو جائے گی۔‘‘ اور جب مسعود رقعہ لے کر بنگلے سے نکلا تو رات چھا چکی تھی اور سڑکوں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس نے ایک تانگہ کرایہ پر لیا اور سڑکوں پر یونہی بے مقصد گھومتا رہا۔ نو بہار ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا اور پھر ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ شرفاء کے کمرے میں جا کر اس نے ہاف سیٹ چائے کا آرڈر دیا اور دیر تک آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا۔ جب وہ اسٹیشن سے نکلا تو نو بج چکے تھے۔ اس نے ٹانگہ باغ کے قریب چھوڑ دیا اور پیدل چلنے لگا۔ سڑکوں کی چہل پہل کم ہونے لگی۔ سیر کرنے والوں کی ٹولیاں باغ سے نکل کر خراماں خراماں گھروں کو جارہی تھیں۔ چوراہوں کے سنتری جاچکے تھے اور سنیماؤں کے سامنے کی رونق اندر ہال میں سمٹ گئی تھی۔ مسعود نے اندھیری گلی میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر پھونس اٹھا کر گپھامیں داخل ہو گیا۔ ریباں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور سلفہ بھرے سگریٹ کا دم لگا کر بولی، ’’آگیا راجہ نل آگیا۔‘‘
رکنے کباڑیے نے کھنکار کر کہا، ’’آنے دو۔ آگے کون سے ننگ بیٹھے ہیں۔‘‘ لالونے اپنی کانی آنکھ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ’’لال اوئے۔ پہلی تاریخ سے پہلے کیسے درشن دیے۔ ابھی تو چاند چڑھنے میں کافی دیرہے؟‘‘ مسعود مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ چیتونے کہا، ’’لے، بھمبیری، چاند مکھن، چاند ہیرا۔ چاند چڑھ گیا چڑھ گیا۔ نہ چڑھا نہ چڑھا، نشہ جو ہوا۔‘‘ اس پر سب ہنسنے لگے۔
جب مسعود جوتا اتار کر دری پر بیٹھ گیا تو رکنے نے پوچھا، ’’پھر کچھ ہو جائے چھوٹی سی بازی؟‘‘
’’لے واہ، چھوٹی کیوں لالا۔‘‘ کانے نے کہا، ’’بازی ہو تو اگڑبم ہو، نہیں تو نہ سہی۔‘‘ رکنا بولا، ’’ہم تو اگڑبم ہی کھیلتے ہیں، لیکن بابو ذرا نرم ہے، اس لیے لحاظ کرناہی پڑتا ہے۔‘‘ لالو کانے کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے کہا، ’’شرع میں کیا شرم۔ بازی میں کیا لحاظ۔ بازی وہ جس میں چمڑس ہو جائے۔‘‘ مسعود نے کوئی جواب دیے بغیر دو سو کے نوٹ نکال کر دری پر رکھ دیے اور چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ دیے کی لو اونچی کر دی گئی اور بازی شروع ہو گئی۔ آخری پتا دری پر پھینک کر مسعود نے رکنے کے آگے سے دو سبز نوٹ اٹھا کر اپنے نوٹوں میں رکھ لیے اور انہیں آگے دھکیل دیا۔
ریباں نے گردن پھیر کر کہا، ’’تیرے صدقے، انگو ٹھی بنوادے۔‘‘ ڈھلن نے ڈکار لے کر کہا، ’’تیرے صدقے، کنواں لگوادے۔ الٹا لٹک کر مالک سے ملوں گا۔‘‘ رکنے کباڑیے نے صدری سے سو سو کے چار نوٹ نکال کر اپنے سامنے رکھ لیے اور جھلا کر لالو سے کہنے لگا، ’’کانے بیمبڑ پنکھا تو کر، گرمی سے جان نکل رہی ہے۔‘‘ کانا بیمبڑ پنکھا کرنے لگا تو مسعود نے ہاتھ سے اشارہ کرکے آہستہ سے کہا، ’’ذرا ہولے۔ دیا نہ بجھ جائے۔‘‘
اور بازی پھر شروع ہو گئی۔
دیدی بستر پر بے معنی سی کروٹیں بدل رہی تھی اور اس کے قریب آرام کرسی میں دراز امی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے تپائی تھی جس پر مسعود چائے پی کر گیا تھا اور اب اس تپائی پر امی کا پرس اور کٹ کیٹ کا ایک پیکٹ پڑا تھا۔ دیدی جاگتے میں بڑبڑا رہی تھی اور امی خاموشی سے اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن رہی تھی۔
بازی ختم ہو گئی اور مسعود نے رکنے کے چار سو سمیٹ کر اپنے نوٹوں میں ملا لیے۔ کانے نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے رکنے کو دیکھا اور بولا، ’’لالا!‘‘
رکنے نے کہا، ’’پھر کیا ہوا؟ ابھی تو بڑی مایا ہے۔ بابو کو جی بہلانے دے۔‘‘ اور اس نے دو سو کے نوٹ نکال کر آگے رکھ لیے۔ مسعود نے کہا، ’’یوں نہیں۔ تخت یا تختہ۔‘‘ اور پھر سارے نوٹ آگے دھکیل دیے۔ رکنے نے کہا، ’’یوں تو یوں سہی۔‘‘ اور چھ اور سبز نوٹ نکال کر اگلے نوٹوں پر ڈال دیے۔ تاش کے پتے پھر انگلیوں میں ناچنے لگے۔
امی نے چور آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا اور ہولے سے کہا، ’’ابھی تک آیا نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے؟‘‘ پھر اس نے کٹ کیٹ کے پیکٹ کو انگلی سے دبا کر دیکھا جو گرمی کی وجہ سے ذرا لجلجاہو گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لاکر امی نے کٹ کیٹ کے پیکٹ پر چھڑکا اور پھر کرسی پر دراز ہو گئی۔ دیدی نے قہر آلود نگاہوں سے امی کو دیکھا اور پھر کروٹ بدل لی۔ آخری پتہ پھینکنے سے پہلے مسعود نے رکنے کے نوٹ پھر اٹھا لیے اور پتہ چوم کر اس کی گود میں پھینک دیا۔ لالو کا نادم بخود پنکھا کیے جارہا تھا۔ چیتو، ڈھلن اور بھمبیری فرش پر سوئے ہوئے تھے اور ریباں دیوار کے ساتھ لگی اونگھ رہی تھی۔ رکنے نے لالو کی طرف دیکھا اور شرمندگی ٹالنے کے لیے دو نوٹ نکال کر اپنے سامنے رکھ لیے۔ مسعود نے کہا، ’’بس دو سو! کوئی اور جیب دیکھ، لالا۔ شاید اس میں سبزے پڑے ہوں۔‘‘
لیکن رکنا کوئی اور جیب دیکھنے پر رضا مند نہ ہوا۔ لالو کانا بولا، ’’کل سہی بابو۔ بولتی بند ہو جائے گی۔ لے یہ ایک دس روپے کی گرم جس یاروں کی بھی رہی۔‘‘ اور اس نے رکنے کے دوسو پر دس اور رکھ دیے۔۔۔ تاش بانٹی جانے لگی۔
امی نے دیدی کے سرہانے تلے ہاتھ پھیر کر اس کی گھڑی نکالی اور اپنے آپ سے کہا۔
’’ایک بج گیا۔‘‘
پھاٹک ذرا سا ہلا۔ امی تیز تیز قدم اٹھاتی ادھر گئی۔ اس نے بولٹ کھولنے سے پہلے چوڑی دراڑ میں سے باہر جھانک کر دیکھا۔ ایک خارش زدہ کتا پھاٹک کے ساتھ اپنی کمر رگڑ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر آکر پھر اسی طرح بیٹھ گئی۔
بازی ختم ہو گئی اور مسعود نے دوسو دس روپے اٹھا کر اپنے نوٹوں میں شامل کر لیے اور رکنے سے پوچھا، ’’اور؟‘‘ رکنے نے معنی خیز نگاہوں سے لالو کو دیکھا اور منہ پونچھ کر بولا، ’’بس!‘‘ نوٹوں کی گڈی بنا کر مسعود نے سامنے کی جیب میں ڈال لی۔ جوتا پہن کر کھڑا ہو گیا اور سوئے ہوئے بیچاروں پر نگاہ ڈال کر بولا، ’’اچھا، استاد، پھر سہی پہلی تاریخ کو۔‘‘
رکنے اور لالو نے کوئی جواب نہ دیا اور مسعود خاموشی سے چل دیا۔ پھونس سے گذر کر اس نے تازہ ہوا میں ایک لمبا سانس لیا اور اندھیرے کی گود میں مڑتی ہوئی بے جان گلی کو دور تک محسوس کیا۔ پھر وہ اپنے گریبان کے بٹن کھولتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ تو کل اٹھارہ سو ہوئے اور گلریز نے دوہزار مانگے ہیں۔ باقی دوسو کا بندوبست کیوں کر ہوگا اور وہ ابھی باقی دوسو کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کے گلے میں صافہ ڈال کر اسے زمین پر گرا یا۔ گرتے ہی ایک تیز دھار چاقو کا لمبا پھل اس کے سینے سے گزر کر دل میں اتر گیا۔
ایک آواز نے کہا، ’’کانے بیمبڑ یہ کیا کیا۔۔۔ نوٹ نکال نوٹ۔‘‘ کانے بیمبڑ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالنے کی کوشش کی مگر چاقو کا پھل نوٹوں کو پروتا ہوا پسلیوں میں پیوست ہو چکا تھا۔ اس نے زور لگاتے ہوئے کہا، ’’لالا نکلتے نہیں۔‘‘ اور جب لالا نوٹ نکالنے کو جھکا تو گلی کے دہانے پر سپاہی سیٹیاں بجانے لگے اور وہ دونوں مسعود کو یونہی چھوڑ کر بھاگ گیے۔ مسعود نے زور لگا کر چاقو باہر نکالا اور اسے پرے پھینکا۔ پھر اس نے خون آلود نوٹوں کی گڈی جیب سے نکالی اور اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ پیٹ کے بل لیٹ کر اس نے نوٹ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیے اور اپنا ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ کہنی کو زمین پر دبا کر اس نے آگے گھسٹنا چاہا لیکن جونہی کہنی اس کے پہلو سے آکر لگی اس کا ہاتھ زمین سے جاٹکرایا اور اس کی جیب سے ایک کروشیا نکل کر باہر گر پڑا۔ مٹھی میں پکڑے ہوئے نوٹوں کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا،
’’امی۔۔۔ می۔۔۔ میں۔۔۔ امی۔۔۔‘‘ لہو کی آخری بوند زمین پر گری اور اس کی مٹھی ڈھیلی ہو گئی۔
امی نے ٹھنڈے پانی میں انگلی ڈبو کر ایک قطرہ کٹ کیٹ پر ٹپکاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، ’’ابھی تک آیا نہیں!‘‘
اشفاق احمد